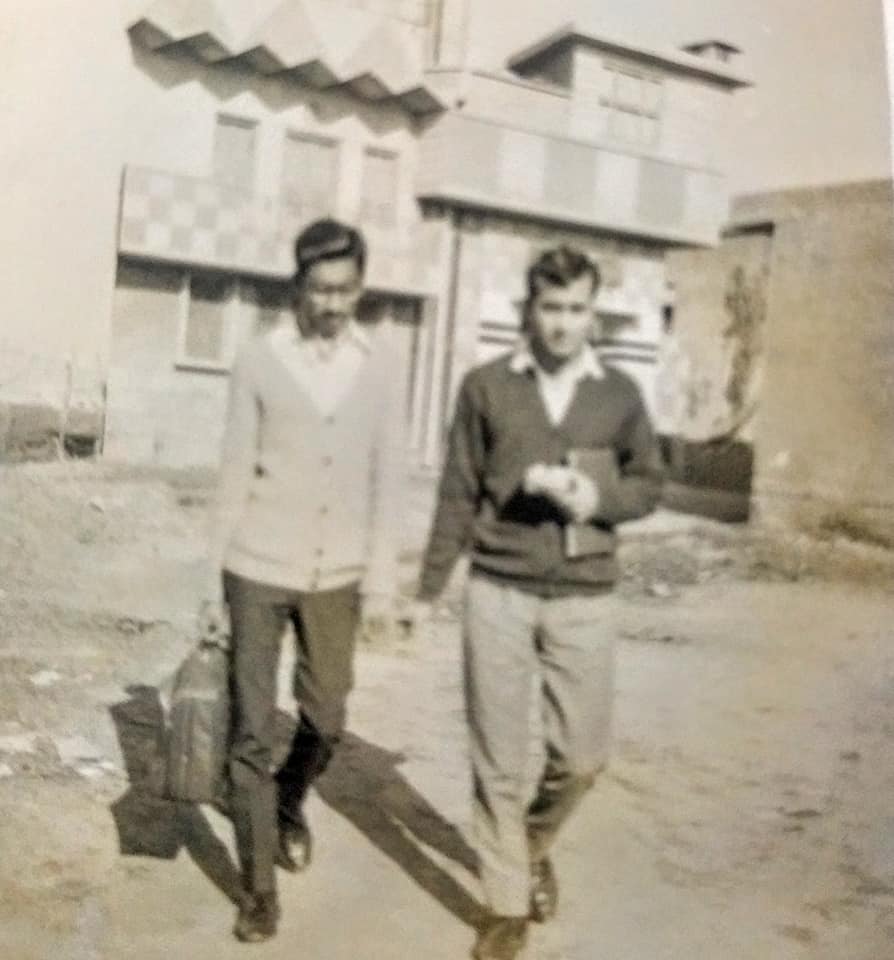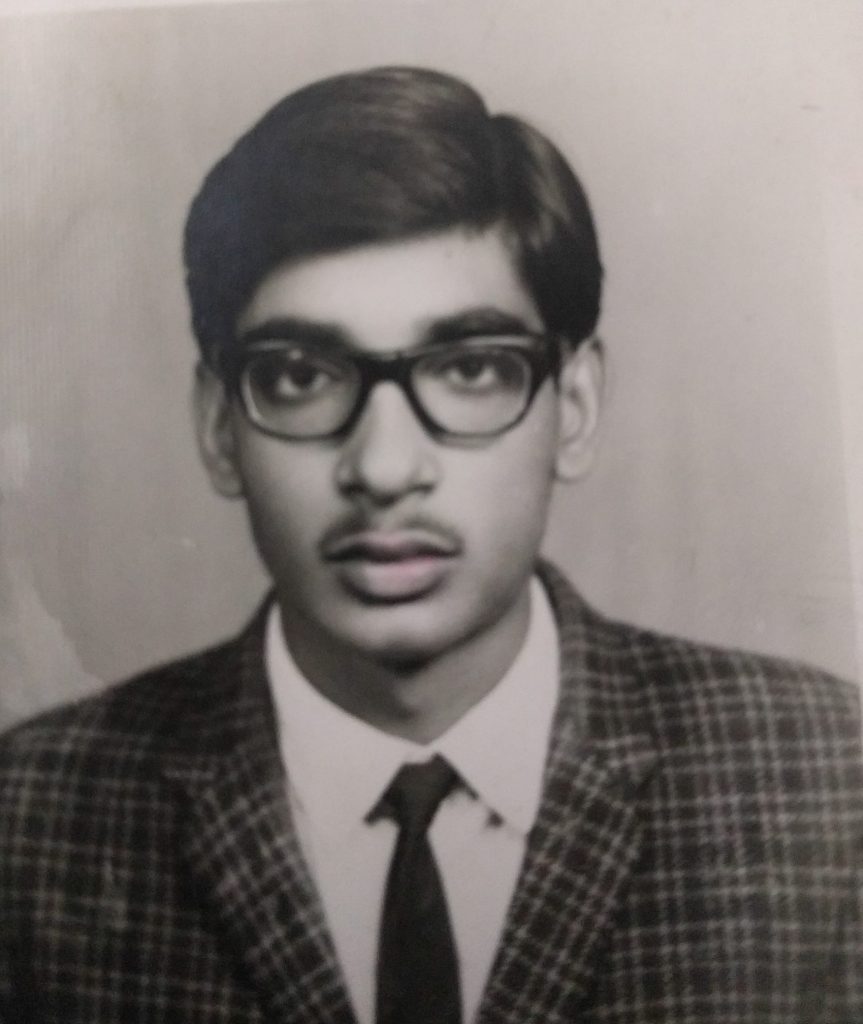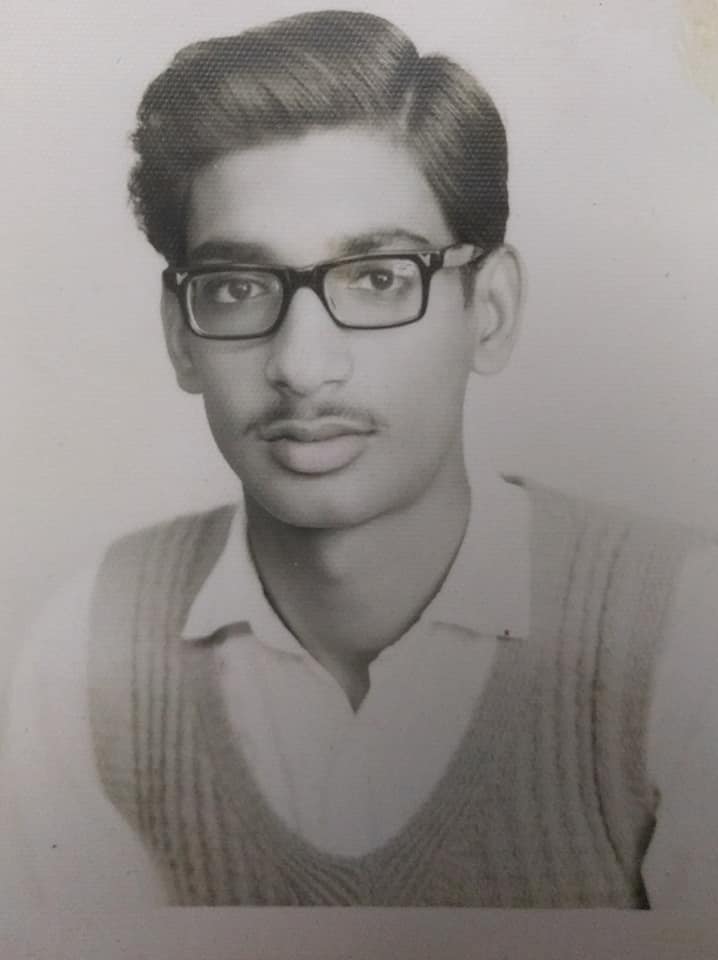میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ بنگلہ دیش نامنظور تحریک کی افادیت کیا تھی اور اس سےسرکاری اور پرائیوٹ املاک کی بربادی کے سوا کیا حاصل ہوا؟کیا ہمارے نامنظور کرنے سے بنگلہ دیش پلٹ کر مشرقی پاکستان بن جاتا؟ میں شاید کُند ذہن ہوں کہ بعض حکومتی اقدامات میری فہم سے ورا رہتے ہیں مثلاً ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جب کہ اس کے قریبی ہمسائے اُسے تسلیم کر چکے۔چلیں اس میں کوئی مصلحت ہو گی مگر بنگلہ دیش کے سلسلے میں ایک تاریخی صداقت کو جھٹلا کر ہم کیا مفاد حاصل کر رہے تھے اور پیہم گھیراؤ جلاؤ کے عمل سے عام شہری کو کیا پیغام دے رہے تھے؟اقبال نے کہا تھا’جُدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی”مگر یہاں ہمیں معکوس صورتِ حال کا سامنا تھا اور اس کا خمیازہ ان طالب علموں نے بُھگتا جو حصولِ علم کی کوشش میں سنجیدہ تھے۔
گاؤں پلٹنے کے بعد لاہور کے پُرسکون ہونے کی خبر ملنے تک مجھے کوئی خاص کام سوائے گھومنے اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے تھا ہی نہیں۔اس دوران میں طالب حسین کی ضد پر ابّاجی نے ایک بائیک یاماہا100سی سی خرید دی تھی۔حق نواز کے پاس شیل کی ہیوی بائیک تھی اور میرے ایک اور دوست کے پاس ٹرامف سو کبھی میاں چنوں،کبھی تلمبہ اور کبھی ہٹھاڑ کی دھول پھانکی جاتی۔خادم رزمی اور ساغر مشہدی کے ساتھ نششت جمتی،جس میں مائی صفورہ سے صاحب زادہ ارشاد قمر بھی آ شامل ہوتے۔کبھی میاں چنوں میں گِل ورائٹی سٹور پر چلا جاتا جو جمیل اقبال گِل نے قائم کیا تھا اور وکالت کرنے کے ارادے سے تائب ہو کر اپنے آبائی پیشے سے مناکحت کر لی تھی۔یہی سٹور میری ڈاک کا ٹھکانہ بھی تھا۔ساغر مشہدی نے تلمبہ رزمی صاحب کے سکول کے قریب تیس روپے ماہانہ پر ایک دکان کرایہ پر لے کر حکمت کی دکان کھول لی تھی مگر اس میں مریضوں کی بجائے شاعروں کا جمگھٹ لگا رہتا تھا۔خان غضنفر روہتکی کی دکان کا پھیرا بھی روز کا معمول تھا اور وہ تازہ غزل اور کڑک چائے سے تواضع کرتے تھے۔
انہی دنوں شمیم اکبر آبادی سے ملاقات کی سُوجھی اور رزمی صاحب اور ساغر مشہدی کو میاں چنوں پہنچنے کا کہہ کر میں گل ورائٹی سٹور پر ان کا منتظر رہا۔شمیم صاحب اُس وقت میاں چنوں کی شعری روایت کے اکلوتے وارث تھے اور مین بازار میں تکہ کباب لگاتے تھے۔وہ کافی بڑی دکان پر قابض تھے مگر اندر کھانے کے کمرے پر کمرے سے زیادہ کسی متروک مندر کا گمان گزرتا تھا۔پہلی اور اس کے بعد ہر ملاقات کا اُصولی ضابطہ یہ ٹھہرا کہ ہم آتے ہی کباب روٹی کا آرڈر دیتے۔جب کھانا لگا دیا جاتا تو شمیم صاحب ہمارے پاس آ بیٹھتے اور مشاعرہ برپا کیا جاتا۔وہ توندیل تو نہیں تھے مگر ان میں اکبر آباد کی ساری خاصیتیں تھیں۔سانولا رنگ،مغلیہ سٹائل زلفیں گردن پر خم کھائی ہوئی،ہونٹ پان سے بھڑکے ہوئے،منجھلے قد اور ڈھیلے بدن پر پیٹ کا خم قدموں کی ذرا سرزنش کرتا ہوا۔بچپن سے میں انہیں اسی طرح دیکھتا آیا تھا کہ وہ اچھے گوشت کی خریداری کے لیے سویرے کوٹ سنجان سنگھ جانے کے لیے بس کے انتظار میں ٹی چوک پر کھڑے ملتے تھے مگر اس مندر میں اُن کی آرتی اتارنے کا آغاز اب ہوا تھا۔ہر بار کھانے کےبعد چائے اُن کی طرف سے پلائی جاتی اور وہ’شمیم ِخستہ تن’اور’شمیم ِزار’ کی لازمی بندش کے ساتھ مقطع تک رسائی پاتے۔حالاں کہ یہ دونوں صفات ان میں مفقود تھیں۔اس کھانے کا بل مَیں دیتا تھا اس لیے اُن کی نظر میں مَیں ساغر اور رزمی صاحب کے مقابلے میں بہتر شاعر تھا۔حالاں کہ رزمی صاحب کی جدت طرازی اور خلّاقی بِلا شُبہ بے مثل تھی اور اگر وہ زیادہ پڑھے ہوتے اور عالمی ادب سے لگاؤ رکھتے تو شاید ہی اس علاقے کا کوئی شخص ان کی تخلیقی صلاحیت کو چُھو پاتا۔یہی مسئلہ ساغر مشہدی کا بھی تھا۔اس پر وہ غزل سے معاملہ نہیں کر پا رہے تھے جب کہ مسدس کہنے میں وہ بہت سُبک دست اور مسُمّط نظم کی تعمیر کرنے میں خاصے مشّاق تھے۔
شمیم اکبر آبادی کی غزلیں کلاسیکی رنگ لیے ہوتی تھیں اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی مگر وہ روایت سے اس شدّت کے ساتھ جُڑے تھے کہ پامال مضامین کی جگالی پر اُتر آئے تھے۔قافیہ ردیف کے اختلاف کے باوجود ان کی ہر غزل اُن کی پہلی غزل کا پرتو ہوتی تھی اور لگتا تھا جیسے ان کی شاعری فکری الزائیمر کا شاخسانہ ہے۔خود میری حالت شاید اس سے مختلف نہیں تھی تاہم رزمی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں عمودی سفر میں ہوں اور تیزی سے اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں جب میں ایک طیّارے کی طرح فضا میں ہموار پرواز کے لائق ہو جاؤں گا۔معلوم نہیں اس میں کتنی سچّائی تھی مگر یہ ضرور تھا کہ ادبی پرچے مجھے خوش دلی سے چھاپ رہے تھے اور میں اپنے ہم عصر لکھنے والوں کے حلقے میں شناخت بنا رہا تھا۔
رزمی صاحب زُود گو تھے تو کم گو مَیں بھی نہیں تھا۔ہر ملاقات پر ہمارے پاس سُنانے کو بہت کچھ ہوتا تھا۔وہ اُن دنوں تلمبہ اور اس کے گردونواح کے شاعروں کے کلام پر مشتمل ایک انتخاب شائع کرنے کی فکر میں تھے۔اس کے لیے میرے سمیت سولہ شاعروں کا کلام یکجا کیا گیا اور مرتب کی حیثیت سے خان غضنفر روہتکی کا نام دیا گیا۔دیباچہ ملتان کے ایک ادیب شیر احمد خاموش کا تھا اور شعرا کے تعارفی شذرے رزمی صاحب کے قلم کی عطا تھے۔’تاروں کی بارات’ نام کا یہ انتخاب اتنی تاخیر سے اور اخباری کاغذ پر اتنا بُرا طبع ہوا کہ شاید ہی کسی شاعر نے اسے دل سے سراہا ہو۔میں نے اس انتخاب میں شامل کلام اپنی کسی کتاب کا حصہ نہیں بنایا مگر میرے فکری سفر کے محاکمے کے لیے اس کو سامنے رکھنا بہرطور سودمند ہو سکتا ہے۔
انہی جبری تعطیلات کے دوران میں ایک بار رزمی صاحب کی خواہش پر میں اور وہ بائیک پر کبیر والا جا کر بیدل حیدری صاحب سے ملے۔انہوں نے چائے پلائی اور کچھ عارفانہ گفتگو کے بعد،جس کے بیچ وہ بار بار اُٹھ کر اپنی دکان کے پردے کے پیچھے گم ہو جاتے تھے،اپنی کچھ غزلیں سُنائیں جو مجھے کچھ خاص خوش نہیں آئیں۔اس سے پہلے میں اور رزمی صاحب نے رسماً اپنا کلام سُنایا اور بیدل صاحب نے میرے حق میں کچھ ارشاد کیا جس کی تفصیل مجھے اب یاد نہیں۔میرے رنگ ِسخن سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر رزمی صاحب یا علاقے کے کسی اور شاعر کا اثر نہیں سو انہوں نے میری اصلاح کا عندیہ دیا نہ کلام کی سمت مقّرر کرنے کے حوالے سے کوئی بات کی۔ پہلے ہی روز ہمارے مابین ایک دوسرے کے فکری مکاشفوں کے حوالے سے قبولیت اور احترام کا رشتہ قائم ہو گیا اور اُن سے آخری ملاقات تک قائم رہا تب بھی جب وہ ڈاکٹر وزیر آغا کی عظمت کے حُدی خواں تھے اور تب بھی جب وہ احمد ندیم قاسمی کے پرستار ہوئے۔
ایک بار میں اور رزمی صاحب ملتان بھی گئے۔گورنمنٹ کالج میں مشاعرہ تھا۔ملتان اور گردونواح کے بہت سے شاعر موجود تھے مگر میں کسی کو کم ہی پہچانتا تھا۔ہاں ان کے نام اور کلام سے شناسائی ضرور تھی۔اس مشاعرے میں عابد عمیق نے اردو کی ایک بالغانہ نظم سُنائی تھی۔اصغر ندیم سیّد اور محمد امین بھی موجود تھے اور سینئیرز میں اصغر علی شاہ، اسلم انصاری،فرخ درانی،ارشد ملتانی، عاصی کرنالی، حسین سحر اور عرش صدیقی۔مجھے بھی اپنا کلام سُنانے کا موقع دیا گیا اور مشاعرے کے بعد کالج کینٹن پر محمد امین،اصغرندیم سیّد اور دوسرے دوستوں سے نشست رہی۔میرے لیے اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ میرے نام سے آگاہ تھے۔شام کو ہم ارشد ملتانی صاحب کے گھر پر ان سے ملے جو بوہڑ گیٹ کے کہیں آس پاس تھا۔وہ بھی بہت محبت سے ملے اور سب سے باہمی احترام اور دوستی کا ایک ایسا رشتہ قائم ہوا جو ہمیشہ برقرار رہنے والا تھا۔
مجھے تاروں کی بارات’کی دس کاپیاں عطا کی گئیں۔کچھ میں نے خریدی اور اپنے عزیز و اقارب کی نذر کیں۔تب کالج کُھلنے کی نوید پہنچی اور ہم دونوں بھائی لاہور پلٹ آئے۔اتنا وقت ضائع ہو گیا تھا کہ تعلیمی اداروں کا شیڈول برباد ہو کر رہ گیا تھا۔اس لیے گمان تھا کہ اس پر نظر ِثانی کی جائے گی مگر پنجاب یونیورسٹی نے وقت پر امتحان لینے کا اعلان کر کے سب کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔طلبہ امتحان کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے مگر اربابِ اختیار تھے کہ ان کے کانوں پر جُوں تک نہیں رینگ رہی تھی سو جب کالج میں امتحانی داخلہ بھجوانے کا نوٹس لگایا گیا تو مَیں نے داخلہ بھجوانے ہی میں عافیت جانی۔