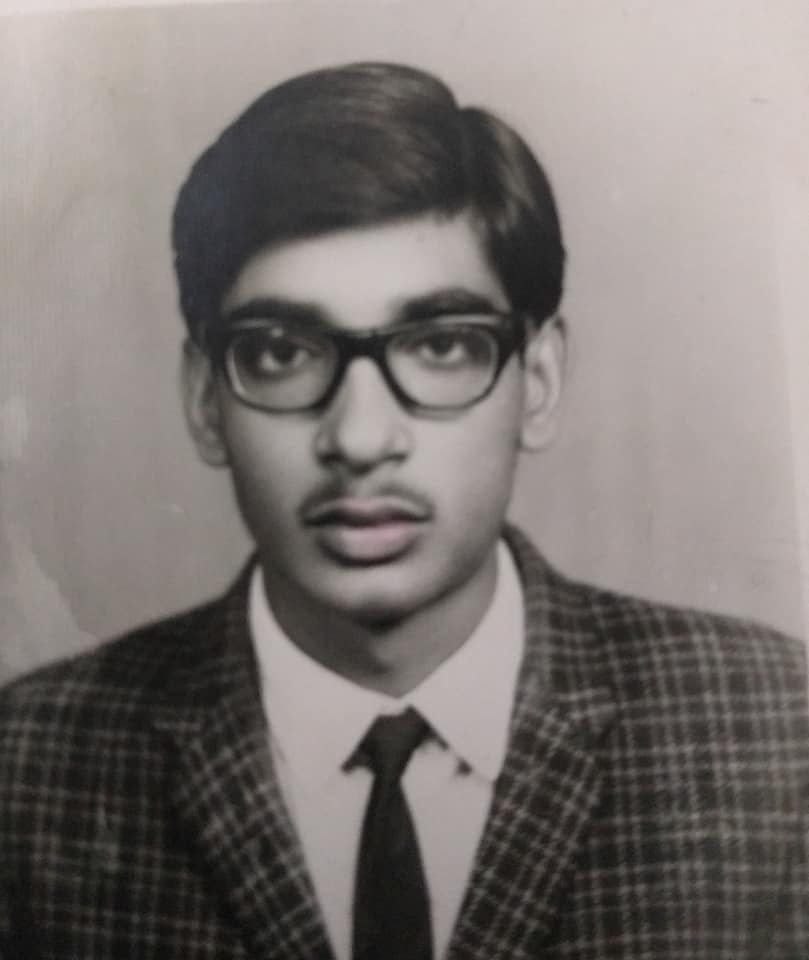فروری 1974ء کے پہلے ہفتے میں نواز نے یونیورسٹی اوریئنٹل کالج میں داخلہ شروع ہونے کی نوید سنائی تو میں اگلے ہی روز لاہور پہنچا اور پراسپیکٹس لے کر ارود اور پنجابی زبان وادب،دونوں شعبوں میں داخلے کی درخواستیں داغ دیں۔اردو بازارچوک کی حبیب بنک بلڈنگ کے کمرہ نمبر سات میں علی ظہیر منہاس سے نشست جمائی۔شام کو ٹی ہاؤس کا چکر لگا کر اگلے روز گاؤں پلٹنے کا ارادہ تھا کہ نواز اور اورینٹل کالج کے بعض دوسرے دوستوں نے دو روز بعد ترقی پسند طلبہ کے کراچی میں ہونے والے کنوینشن میں شرکت کے لیے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔میں اس نیّت سے آیا تو نہیں تھا مگر کراچی دیکھنے اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی ہوس اور اس سے زیادہ اس تاریخی اجلاس کا حصہ بننے کے شوق میں ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا اور اگلی دوپہر لاہور کے طلبہ کا یہ وفد خصوصی ٹرین سے جو پشاور سے گوجرانولہ تک کے طلبہ کو لےکر پانچ گھنٹے کی تاخیر سے سہ پہر کو لاہور پہنچی اور جس کی دو بوگیاں لاہور کے طلبہ و طالبات کے لیے مخصوص تھیں،کراچی کے لیے روانہ ہوا۔اس ادا کے ساتھ کہ یہ طلبہ کی مرضی سے رکتی اور چلتی تھی اور راہ میں آنے والی ہر سومنات کو محمود غزنوی کی طرح روندتی جاتی تھی۔پہلے رینالہ کے کسان اسٹیشن کے قرب و جوار میں کنّو اور مالٹے کے باغوں پر دھاوا بولا گیا پھر ساہیوال اسٹیشن کو لُوٹنے کی باری آئی اور کیفیت یہ ہوئی کہ پنجاب کراس کرنے سے پہلے ہی ہر سٹاپ خالی ملنے لگا۔یہ ٹرین عام مسافروں کے لیے نہیں تھی اور نہ ہی اس پر راہ میں منتظر طلبہ کے سوا کسی کو سوار ہونے کی اجازت تھی مگر طلبہ کے سیلِ بے اماں کے آگے بند کون باندھتا۔ہماری بوگی میں روہڑی سے کچھ سندھی مسافر بٹھا لیے گئے اور نہ معلوم کیسے نواز سمیت دوستوں کے ایک وفد نے ان کے ساتھ ایک روپیہ بوٹ رکھ کر فلاش کھیلنی شروع کی اور یہ سلسلہ رات بھر جاری رہا۔ٹرین ضرورت سے کہیں کم رفتار کے ساتھ چلتی تھی اور جہاں جی چاہتا تھا،زنجیر کھینچ کر روک لی جاتی تھی۔ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سندھ کی ایک تقریباً ویران جگہ پر رک کر کچھ طلبہ سامنے دکھائی دینے والے گاؤں میں کسی سے ملنے چلے گئے اور ان کی واپسی تک کم و بیش تمام مسافر نیچے اتر کر طرح طرح کے کام کرتے رہے،جن میں نواحِ دہلی کے صبح کے وقت داخلے کے منظر کا اعادہ بھی شامل تھا(سمجھوتہ ایکسپریس لاہور سے فجر کے وقت دہلی پہنچتی تھی تب شہر کے آغاز سے پہلے ریلوے کی پٹڑیاں لوٹا اور پانی کی بوتل بردار لوگوں سے بھری ہوتی تھیں جو ٹرین کی طرف رُخ کیےحوائج ِضروریہ سے فارغ ہو رہے ہوتے تھے۔ان کی تعداد گنتی سے باہر ہوتی ہے۔کہیں بھی کھڑے ہو کر کسی بھی دیوار کو سیراب کرنے کی ادا دہلی اور ڈھاکہ کے باسیوں میں مشترک ہے اور ان دونوں شہروں کی فضا پر غالب بُو پیشاب کی ہے)۔لاہور کے مختلف اداروں سے شامل ہونے والے طلبہ و طالبات دو سو سے کم کیا ہوں گے مگر مجھے نواز،انیس،میاں سعید،عبدالغفور،رانا تصور حسین،ضیا آفتاب،رانا سہیل،محمد جہانگیر،محمد باقر،مختار اور نشاط کاظمی کے نام ہی یاد ہیں۔راہ میں فلاش کھیلنے کے نتیجے میں نواز اپنے مالی اثاثے سے پوری طرح فارغ ہوا تو مجھ پر انحصار کی ضرورت درپیش ہوئی۔میں فلاش دیکھتا ضرور تھا کہ یہ کام ہاسٹلز میں بھی ہوا کرتا تھا مگر اس کے کھلاڑیوں یا شیدائیوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔اب دوستوں کے اصرار اور سندھی ہمراہیوں کے للکارنے پر پال میں صرف اس شرط پر بیٹھا کہ ایک گھنٹے سے زیادہ اور پچاس روپے( جو آج کے پانچ ہزار کے برابر تھے) سے زیادہ نہیں کھیلوں گا۔میں نے ایسا ہی کیا مگر اپنی ناتجربہ کاری کے باوجود وہ رات میری تھی۔ایک ہی گھنٹے میں ساتھیوں کی ہاری ہوئی رقم واپس آ چکی تھی بل کہ کچھ فائدے ہی میں رہے۔میں نے کراچی یاترا کے دوران میں کسی کی رقم اّسے باقاعدہ نہیں لوٹائی۔منوڑا،ہاکس بے،کیماڑی،صدر،زیرو پوائنٹ،لیاقت آباد وغیرہ کی سیر اور مزار ِقائد پر حاضری کا خرچ میں نے ہی اٹھایا مگر انھی کے پیسوں سے اور شاید یہ ان کے اور میرے حق میں بہتر رہا۔ہماری ٹرین لگ بھگ چھتیس گھنٹوں کے بعد کراچی پہنچی۔کینٹ اسٹیشن سے ہمیں نیشنل اسٹیڈیم لے جایا گیا۔لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام تھا مگر ہمیں گراؤنڈ میں خیمے الاٹ کیے گئے۔تاہم بستر وغیرہ کا معقول انتظام تھا اور نہانے دھونے کو کھلاڑیوں کے لیے مخصوص غسل خانے دستیاب تھے۔خیمے میں بستر پر قبضہ کرنے اور سامان رکھنے کے بعد میں نے تازہ دم ہونے کے لیے غسل خانوں کا رُخ کیا۔غسل کرنے کے لیے شاور کھولنے کی دیر تھی کہ انتہائی یخ پانی کی زور دار دھار نے لپیٹ میں لے لیا۔اُف خدایا! میں اس حماقت اور اذیت کو آج تک نہیں بھولا۔پتا نہیں کوئی خصوصی اہتمام کیا گیا تھا یا کراچی کے موسم کی تاثیر تھی کہ دریائے سوات اور کنہار کا پانی بھی اس پانی کی ٹھنڈک کے آگے پانی بھرتا تھا مگر اب نہائے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔سو جیسے تیسے نہا کر کپڑے بدلے اور نواز کو ساتھ لے کر کینٹین سے چائے کے دو کپ پئیے تو ہوش قدرے ٹھکانے آئے۔اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نہانے سے پہلے پانی کا درجۂ حرارت معلوم کر کے ہی غسل کی زحمت اٹھاتا رہا۔کراچی قیام کی پہلی ہی رات ہم سب NOPS کے ممبر بنے۔یہ نیشنل آرگنائزیشن آف پراگریسو سٹوڈنٹس کا مخفف تھا۔اس میں شامل ہونے والے تمام طلبہ پہلے مختلف ترقی پسند تنظیموں کے رکن تھے۔اس موقع پر کراچی کے کئی گلوکاروں نے لائیو پرفارم کیا.کراچی کے گٹارسٹ جو بعد میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے مستقل پرفارمر رہے،عالمگیر سے پہلی دفعہ تعارف اسی موقع پر ہوا اور انھوں نے زیادہ تر کشور کمار کو گایا۔خصوصاً”یہ شام مستانی مدہوش کیے جائے”نے تو رنگ باندھ دیا۔رات کو بون فائر کے وقت تو جیسے کسی میلے کا سماں تھا کہ چاروں صوبوں کے طلبہ کے علاقائی رقص اور گیت تھمنے ہی میں نہیں آتے تھے۔اس ہلّے گُلّے میں طالبات کا حصہ طلبہ سے بڑھ کر تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے نوجوان پاکستانی نسل کوئی نئی کروٹ لے رہی ہے۔اس وقت لاؤڈ سپیکر پر اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی گیت تھا:ہو مبارک آج کا دنرات آئی ہے سُہانیشادمانی ہو شادمانی۔۔۔دوسرا دن گھومنے پھرنے میں گزارا۔تیسرے دن کی رات کنوینشن ہال میں بڑا جلسہ ہوا۔جس کی صدارت ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ہال کو ماؤ اور دیگر مارکسی اور سوشلسٹ رہنماؤں کی تصاویر اور اقوال سے سجایا گیا تھا۔اس ہال میں مختار وغیرہ کے ایما پر "کھر ساڈا شیر اے،باقی ہیر پھیر اے” کے نعرے لگائے گئے اور خوب دھما چوکڑی مچی۔اس نعرے نے بھٹو کو بدمزہ کر دیا اور اس نے انتہائی مختصر تقریر پر اکتفا کر کے جانے میں عافیت جانی۔شاید بھٹو اور کھر کے بیچ مخاصمت کی بنا اسی کنوینشن سے پڑی۔ہم نے دو روز مزید اسی سٹیڈیم میں گزارے۔جی بھر کر گھومے پھرے۔اپنے عزیزوں کے لیے معمولی تحائف خریدے اور اُسی سپیشل ٹرین سے لاہور مراجعت کی۔واپسی کے سفر کی کتھا جانے کی کتھا سے مختلف نہیں تھی۔ایک جگہ سینکڑوں طلبہ کے ایک جتھے نے پونے گنّا کے کھیت پر یلغار کی تو چند دیہاتی بندوق لے کر مرنے مارنے پر اُتر آئے۔ان کی عورتیں ماتم کرتی ہوئی بین کرنے لگیں۔ادھر طلبہ بھی پستول لہراتے ہوئے مقابلے پر اُتر آئے۔اُن دیہاتیوں کا غصہ اور رنج فطری تھا۔وہ بین آج بھی میرے دل پر لکھے ہیں۔افسوس شاید میرے سوا ان کا کوئی ہم درد نہ تھا۔اپنے دوستوں کو بڑی مشکل سے اس تصادم سے باز رکھا۔ان غریب کسانوں کی مدد کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں تھی مگر شاید اس سے زیادہ کچھ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔یہ کہانی رینالہ پہنچنے پر دہرائی گئی اور ہم لوگ جب لاہور اترے تو کئی طلبہ کے تکیوں کے غلاف مالٹوں سے بھرے تھے۔اس سفر نے مجھے طلبہ سیاست سے متنفر کر دیا مگر میرے اندر کا ترقی پسند پھر بھی نہیں مرا۔اگرچہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ترقی پسند طلبہ کبھی کسی تنظیم میں نہیں ڈھل سکتے اور وہ ایک متشدد ہجوم ہی رہیں گے۔لاہور پلٹے تو داخلے کی فہرستیں لگ چکی تھیں۔مجھے اردو اور پنجابی دونوں میں داخلے کا حق دار قرار دے دیا گیا تھا۔اردو کی فہرست میں میرا نام چودھویں اور پنجابی شعبے کی فہرست میں پہلا تھا۔انٹرویو کی تاریخ اگلے ہی روز تھی اور مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی کہ کس مضمون میں داخلہ لوں۔نواز تب اردو کو خیرباد کہہ کر پنجابی کی فائنل کلاس میں تھا اور اس کا اصرار تھا کہ اگر مجھے وقت گزاری کے لیے ہی داخلہ لینا ہے تو اس کے لیے پنجابی میں داخلہ لینا ہی مناسب رہے گا۔
Category Archives: درس گاہ
درس گاہ – 52
سراج منیر مولانا متین ہاشمی کے فرزند تھے اور یکم جون 1951ءکو سید پور مشرقی پاکستان (موجودگی بنگلہ دیش)میں پیدا ہوئے۔یہ خاندان غازی پور (یوپی-بھارت)سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان منتقل ہوا تھا۔سراج اپنے والد کے بڑے صاحب زادے تھے اور بلا کے ذہین۔میڑک میں وہ پورے مشرقی پاکستان میں اوّل آئے۔زوال ِڈھاکہ کے بعد یہ خاندان کراچی منتقل ہوا اور پھر لاہور۔سراج سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہ بی۔اے کر چکے تھے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم-اے انگریزی میں داخلہ لینے والے تھے۔یہی زمانہ تھا جب میں اورینٹل کالج میں داخلے کے انتظار میں تھا۔فرق صرف یہ تھا کہ اردو یا پنجابی میں ایم-اے کرنا میری منزل نہیں تھی جب کہ سراج منیر اپنی منزل سے بخوبی آگاہ تھا اور میری طرح اندھیری رات کا مسافر نہیں تھا۔
دو چار ملاقاتوں ہی میں کُھل گیا کہ سراج منیر اور ہمارے مطالعے میں ایک اور دس کی نسبت ہے۔وہ اردو اور فارسی کلاسک کو کھنگال چکا تھا اور یہاں یہ عالم تھا کہ کلاسک سے آشنائی کے عمل کا ابھی آغاز ہی نہیں ہوا تھا۔میں نے نسیم حجازی سے انتظار حسین تک کو تو پڑھ رکھّا تھا مگر کلاسیکی شاعری اور نثر سے واسطہ تھا نہ طبیعت اسے پڑھنے پر مائل ہوتی تھی۔اس لیے جب سراج کی گفتگو میں کلاسیکی ادب کے حوالے آتے اور وہ کسی شعر یا نثر پارے کو اپنی دلیل کی صداقت کو بڑھانے کے لیے پیش کرتا تو میں سوائے داد دینے کے اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔اس پر اس کی خطابت۔زبان اور صنائع لفظی و معنوی کی خوبیوں سے بھری۔ایک دل موہ لینے والی تاثیر اور دماغ کو مسخّر کرتے دلائل سے لبالب۔جس میں انگریزی کے توسط سے عالمی ادب کے وسیع مطالعے کا تڑکا لگا ہوا یعنی سونے پر سہاگا ہی نہیں کچھ اس سے فزوں تر۔بس وہ کہے اور سُنا کرے کوئی۔یہی وجہ تھی کہ جب یہ آواز حلقۂ اربابِ ذوق میں گونجی تو اپنی جگہ بناتی ہی چلی گئی۔سراج منیر نے میری میز کو بدستور سجائے رکھّا مگر بہت جلد وہ لاہور کے ہر معقول ادیب و شاعر کا محبوب بن گیا۔انتظار حسین،پروفیسر سجاد باقر رضوی،سجاد رضوی،سہیل احمد خان،مسعود اشعر،محمد سلیم الرحمٰن،زاہد ڈار اور تبسّم کاشمیری جیسے نابغے اس کی راہ دیکھنے لگے اور مجھ سمیت میری عمر کے اکثر نوجوان اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔
سراج ہی کے توسط سے میں کراچی کے بہت سے لکھنے والوں سے آشنا ہوا اور دوستوں کا ایک وسیع حلقہ وجود میں آیا۔اُس نے میرے فکری منہاج کے تعین میں بھرپور حصہ لیا،اس کے باوجود کہ فکری لحاظ سے ہم دو الگ بلکہ متضاد رویوں کے لوگ تھے۔اس کی نسبت دائیں اور میری بائیں بازو سے تھی مگر اس میں بھلائی کا پہلو یہ تھا کہ وجود کی تکمیل ان دونوں کے ملاپ سے ہوتی ہے۔کلوینو کے دو لخت شہزادے کی طرح ہر حصہ اپنی جگہ مکمل ہو کر بھی دوسرے حصے کو پائے بغیر سود مند نہیں ہو سکتا اور میری اور سراج کی ذات میں خیر کا پہلو شاید ہمارے اختلاف ِرائے کے استحکام ہی سے ممکن تھا۔
سراج نے شاید ٹھان رکھّی تھی کہ وہ میری شاعری کی تحسین کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہے گا۔میں نے جب بھی کسی ادبی حلقے میں کوئی چیز تنقید کے لیے پیش کی۔وہ میری مدح کو وہاں موجود ہوتا تھا۔یہی نہیں اردو اور عالمی ادب کے حوالے سے اس کے تعین ِقدر میں اس قدر اضافہ کرتا تھا کہ مجھے خود پر فخر محسوس ہونے لگتا تھا اور بعض اوقات یقین نہ آنے پر اس کی اور اپنی دماغی صحت پر شبہ بھی ہوتا تھا مگر سچ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔مجھے معلوم تھا کہ میں بُرا شاعر نہیں ہوں اور معمول سے مختلف بھی ہوں سو اس امر کی طرف نشاندہی کرنے میں کیا برائی تھی؟
سراج منیر تصویری (photo genic) یاداشت کے مالک تھے اور اردو/انگریزی ادب کے حوالے دیتے ہوئے اصل عبارت کو اپنی یاداشت کے سہارے دہرانے پر قادر تھے۔اس سلسلے میں ایک واقعے کا بیان دلچسپی کا حامل ہو گا۔حلقہ کے اجلاس سے پہلے ہم پاک ٹی ہاؤس کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھے گپ ہانک رہے تھے کہ اجلاس شروع ہونے پر پروفیسر شہرت بخاری ہمیں دھکیل کر اجلاس میں لے گئے۔صدارت پروفیسر سجاد باقر رضوی کی تھی۔ادب پارے کا تنقیدی محاکمہ کرتے ہوئے سراج منیر نے کسی مغربی نقاد کا قول اپنی دلیل کو باوزن بنانے کے لیے دہرایا تو باقر صاحب نے گرفت کرتے ہوئے فرمایا کہ مغربی ناقدین کا حوالہ دے کر اپنی بات کو مؤقر بنانا رواج پایا گیا ہے۔مجھے شبہ ہے کہ جس ناقد کا حوالہ سراج منیر دے رہے ہیں،اس نے شاید ہی کبھی ایسی کوئی بات کی ہو۔اب معلوم نہیں باقر صاحب سراج کے زورِ بیان پر گرفت کر رہے تھے یا اس کی یاداشت کو آزمانا چاہتے تھے مگر سراج کو اُن کا استہزائیہ انداز کھا گیا۔اس نے تڑپ کر بصد معذرت عرض کی کہ اس وقت اس کے پاس مذکورہ ناقد کی کتاب موجود ہے اور اگر جنابِ صدر اجازت دیں تو وہ اپنی دلیل کے حق میں سنائی گئی کوٹیشن کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ کتاب سے پڑھ کر سنانا پسند کرے گا۔باقر صاحب نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اجازت دی اور سراج نے کتاب کھول کر اور صفحہ نمبر بتا کر کم و بیش ایک صفحہ مذکورہ کوٹیشن سمیت پڑھ کر سّنا دیا۔
اجلاس کے اختتام پر ہم دوبارہ اپنی میز پر آ بیٹھے۔میں نے سراج سے کہا کہ ممکن ہو تو مذکورہ کتاب دو ایک دن کے لیے مجھے عنایت کرے۔اس نے کہا کہ آج نہیں۔ہاں کل وہ میرے لیے کتاب لیتا آئے گا اور میں اپنی سہولت سے پڑھ کر اسے لوٹا دوں۔میں نے اصرار کیا کہ جب کتاب موجود ہے تو اسے کل پر کیوں ٹالا جائے اور کچھ زبردستی کرتے ہوئے کتاب چھین لی مگر کھول کر دیکھا تو وہ کشف المحجوب کا کوئی نسخہ تھا۔میں حق دق رہ گیا اور پوچھا کہ اس نے وہ طویل عبارت کہاں سے پڑھی تھی تو سراج نے اپنے سر کو انگلی سے چھو کر کہا”یہاں سے”.
یہ سراج کی کہانی کا ابتدائیہ ہے۔1974 سے اس کی وفات تک اس میں عمودی اسراع کی کیفیت ہے۔مجھے شعر کہہ کر سب سے پہلے اسے سنانا اچھا لگتا تھا اور اس کی شاعری اور تنقیدی مضامین کا پہلا سامع بھی میں ہی ہوا کرتا تھا۔اس کی شاعری میں ایک دل موہ لینے والی تازگی تھی اور مضامین میں نئے پن اور تخلیقی اپج کے ساتھ ساحری کی سطح کو چھوتی دل نشین نثر جو اپنے اندر معانی کا ایک جہان لیے ہوتی تھی۔اس زمانے میں اس نے چند کہانیاں بھی لکھیں جو انتظار حسین اور سریندر پرکاش کے اسلوب سے متاثر ہونے کے باوجود موضوع اور تخلیقی ندرت کی سطح پر منفرد تھیں اور جن میں ہم عصریت کا پرتو بہت واضح تھا۔
سراج منیر کی کہانی لکھنا مجھ پر قرض ہے۔اس لیے بھی کہ یہ میری کہانی کا حصہ ہے اور اس لیے بھی کہ ہماری کہانی ایک دوسرے کی کہانی میں اس طرح دھنسی ہوئی ہے کہ اسے الگ کر کے دیکھنا ضروری ہے۔بہت کچھ ہے جو بتانا ضروری ہے اور بہت کچھ ہے جس کا چھپانا لازم ہے مگر یہ فیصلہ کرنا ابھی لازم ہے نہ ضروری۔ابھی تو وہ گورنمنٹ کالج اور میں یونیورسٹی اورینٹل کالج میں داخلے کے منتظر ہیں اور ہماری گاڑی اسٹیشن سے نکلنے کے انتظار میں ہے۔
درس گاہ – 51
ریڈیو پاکستان لاہور کے پروگرام یونیورسٹی میگزین میں ہم دوست یا ہماری ٹولی ایک ساتھ مدعو کی جاتی تھی۔اس ٹولی میں مابدولت کے علاوہ علی ظہیر منہاس،علی نوید بخاری،ظفر رُباب،امجد
منہاس،نگہت رضوی،زاہد کامران،عبدالحکیم عامر اور اور اختر کاظمی کی حیثیت مستقل تھی۔کبھی کسی نئی آواز کو بھی موقع دے دیا جاتا تھا۔تہتّر کے آخر اور چوہتّر کے اوائل تک ہم کم و بیش ہر پروگرام کا حصّہ بنے جن کی میزبانی پروفیسر قیوم نظر،پروفیسر عارف عبدالمتین،پروفیسر امجد اسلام امجد(جو اُس وقت ابھی لڑکے ہی تھے) اور علی ظہیر منہاس نے کی۔
اس سلسلے میں تین واقعات ایسے ہیں جو اب تک ذہن سے نہیں اترے۔اس لیے ان کا اجمالی ذکر کرنا مناسب ہو گا۔
پروفیسر قیوم نظر کی میزبانی میں ایک پروگرام اقوام ِمتحدہ کی پچیسویں سالگرہ کے موقع پر نشر کیا گیا۔اس کے لیے تمام شرکا کو اقوام ِمتحدہ کے مقاصد کے حوالے سے نظمیں پڑھنا تھیں۔ریکارڈنگ سے پہلے پروفیسر صاحب میری نظم کے دوسرے بند پر معترض ہوئے اور نظم کو پہلے بند پر ہی ختم کرنے کی صلاح دی۔یہ صورت مجھے منظور نہیں تھی سو میں نے شمولیت سے معذرت چاہی تو ساتھی شعرا نے میری شمولیت پر اصرار کیا مگر پروفیسر صاحب اپنی ضد پر اڑے رہے۔ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور طے پایا کہ میں بظاہر پروفیسر صاحب کی بات مان لوں گا مگر ریکارڈنگ کے وقت پوری نظم پڑھوں گا۔بعد میں جو ہو گا دیکھا جائے گا۔سو میں پروگرام کا حصّہ بنا اور پہلے بند پر داد کا سلسلہ جاری تھا کہ میں نے دوسرے بند کو قدرے تیزی سے اس طرح نمٹا دیا کہ میزبان کو خبر ہونے تک میں اپنا کام کر چکا تھا۔عجیب بات یہ کہ کسی نے مشاعرے میں خلل نہیں ڈالا۔بعد میں کینٹن پر چائے پیتے ہوئے پروفیسر صاحب مجھ پر خوب برسے مگر ہم نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کا بتایا اور عرض کی کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پرڈیوسر پروگرام نشر کرتے وقت نظم کو ایڈیٹ کر دیں گے اور آپ اسے میرا آخری پروگرام جانیے مگر جب پروگرام نشر ہوا تو اسے ایڈٹ نہیں کیا گیا تھا۔ہاں میں اگلے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے گیا تو میزبان اور پروڈیوسر دونوں نئے تھے۔آپ کی دلچسپی کے لیے نظم ذیل میں درج کرتا ہوں۔واضح رہے کہ یہ نظم میری کسی کتاب کا حصّہ نہیں:
"پچیسویں سالگرہ پر”
ہمیں یہ خبر ہے
نیویارک کی وہ عجوبہ عمارت
جو سب کی لہو رنگ تیرہ نگاہوں کا مرکز بنی تھی
ابھی تک اُسی شان سے سر اُٹھائے کھڑی ہے
ہمیں علم ہے امن کے دُکھی دل پریشاں پجاری
جو انسانیت کی بھلائی کی خاطر
اندھیری رُتوں میں اکٹھّے ہوئے تھے
ابھی جاگتے ہیں
ہمیں علم ہے جنگ اور نفرت کسی مسئلے کا
تدارک نہیں ہے
ہمیں یہ خبر ہے ہمارے مرّبی
بنی نوعِ انساں کو لاحق مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے جاگتے ہیں
ابھی جاگتے ہیں
۔۔۔۔اگر جاگتے ہیں تو کیوں ہم ابھی تک
اسیر ِشبِ قہرِ آزردگی ہیں؟
اندھیرے کی تہ میں نہاں ہو رہی ہے ہماری بصیرت
بدن ہیں قضا کی شقاوت سے گھایل
اُفق تا اُفق بہ رہا ہے ہمارا لہو خاکداں پر
مسلسل سُکڑتی چلی جا رہی ہے زمیں کارواں ہر
ہمارے سروں پر ابھی تک مسلّط ہیں کیوں یہ مسائل؟
دوسرے واقعے کی نسبت علی ظہیر منہاس کے ایک پرستار سے ہے۔اب میں ان کا نام بھول گیا ہوں مگر اتنا یاد ہے کہ وہ شاعر نہیں تھے اور صرف ریڈیو اسٹیشن دیکھنے کے شوق میں ساتھ ہو لیے تھے۔وہ کچھ چل بے چل سے تھے۔اس لیےانہیں ہدایت کی گئی کہ وہ ریکارڈنگ کے وقت خاموش رہیں گے اور داد دینے کی زحمت نہیں کریں گے۔انہوں نے اس ہدایت پر عمل بھی کیا مگر جب ظفر رباب اپنی غزل کے اس شعر پر پہنچے:
میں نے بارش کی دُعا مانگی تھی فصلوں کے لیے
گھر کی دیوار سے پانی بھلا کیوں رِستا ہے؟
تو وہ اپنی چُپ کو برقرار نہیں رکھ سکے اور ایک تیز رعد جیسی آواز میں گرج کر فرمایا”سبحان اللہ! کیا غُربت ِوطن ہے؟”. اُن کا یہ فرمانا تھا کہ سب حق دق رہ گئے،شاعر اگلا شعر پڑھنے کی بجائے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ پروڈیوسر تڑپ کر اندر چلے آئے۔ریکارڈنگ روک دی گئی۔مہمان کو باہر کا راستہ دکھایا گیا اور بقیہ مشاعرہ اس کے بعد ریکارڈ کیا گیا۔
تیسرے واقعے کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ ایک نئی محبّت کی بنیاد بنا۔اس روز یونیورسٹی میگزین کے مشاعرے میں ایک نیا نام سراج منیر نامی ایک نوجوان کا تھا۔میزبان نے اس نام کو آخر میں درج کر رکھا تھا۔یعنی مشاعرے کا اختتام اُن کی غزل پر ہونا تھا۔مجھے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مگر علی ظہیر منہاس اس معاملے میں بہت حسّاس تھے۔وہ معترض ہوئے اور ان کے موقف کی سبھی نے حمایت کی تو سراج منیر کا نام کہیں درمیان میں درج کر دیا گیا اور انہوں نے اس تبدیلی کو خوش دلی سے قبول بھی کیا۔اُن کی یہ ادا مجھے اچھی لگی۔ریکارڈنگ کے بعد ہم ساتھ ہو لیے۔کنگ سرکل(لکشمی چوک) پر چائے پینے تک ہم دوست بن چکے تھے۔پھر میں انہیں اپنے ساتھ پاک ٹی ہاؤس لے آیا۔مجھے میرے شعری مزاج اور دوستوں کے کراچی میں ایک وسیع حلقے کے باعث "کراچی والا” کہا جاتا تھا اور سراج منیر تو آئے ہی کراچی سے تھے۔اس لیے ہمیں بے تکلّف ہونے میں دیر نہیں لگی۔ہم نے ثروت حسین اور شاہدہ حسن کی شاعری پر بات کی۔قمر جمیل،سلیم احمد،اطہر نفیس،رئیس فروغ وغیرہ کو یاد کیا اور پاک ٹی ہاؤس میں ایک میز پر ساتھ بیٹھنا آغاز کیا۔یہ سلسلہ برسوں پر محیط رہا۔جس کی تفصیل الگ دفتر کی متقاضی ہے۔
یہ وہی سراج منیر ہیں جو بعد میں ادارہ ثقافت ِاسلامیہ کے کم عمر ترین ڈائریکٹر بنے۔کتاب”ملت ِاسلامیہ۔۔تہذیب و تقدیر”کے خالق تھےاور بے مثل شاعر اور نہایت فطین نقّاد۔اُن کی شخصیت کا ایک خفی پہلو ہجو نگار ہونا ہے مگر وہ یہ کام تن ِتنہا سر انجام نہیں دیتے تھے بلکہ محمد خالد اور اس فقیر کی معیت میں تکمیل کو پہنچاتے تھے۔اس کے لیے ایک اجتماعی تخلص”غریب و سادہ و رنگیں”استعمال کیا جاتا تھا جو دراصل "سراج و خالد و ساجد”کی متبادل صورت تھی۔
کبھی اُفتاں کبھی خیزاں غریب و سادہ و رنگیں
تمھارے شہر میں مہماں غریب و سادہ و رنگیں
درس گاہ – 50
سن تہتّر کی یہ ششماہی کئی لحاظ سے یادگار رہی۔سیف زلفی کے حلقۂ اربابِ قلم سے میں نے اپنی مجلسی زندگی کا آغاز کیا۔مجھے یاد ہے جس روز میں نے وہاں تنقید کے لیے نظم پیش کی۔دل میں رد و قبول کے خوف سے عجب دھڑکا تھا مگر خیریت گُزری اور میری نظم کو اسلوب،موضوع اور زبان تینوں حوالوں سے عمدہ قرار دیا گیا۔سیف زلفی کے مزاج میں ایک عجب لپک اور طراری تھی جو اس روز میرے بہت کام آئی اور ان سے ایک طویل نسبت کی بنیاد بنی۔
اسی زمانے میں میں علی ظہیر منہاس اور ظفر رباب کے ساتھ ریڈیو پاکستان لاہور پر متعارف ہوا۔پروگرام یونیورسٹی میگزین تھا اور اس کے پروڈیوسر اسد نذیر تھے۔بعد میں کچھ پروگرام صفدر ھمدانی اور نیلوفر عباسی کے ساتھ بھی کیے۔یہ وہ زمانہ تھا جب ریڈیو میں ایک سے بڑھ کر ایک نابغہ بھرا تھا اور ان کی ادب شناسی اور ادب پروری مسلّمہ تھی۔اس پروگرام میں شرکت کا معاوضہ بیس روپے تھا جو چیک کی صورت میں ادا کیا جاتا تھا اور اس پر دو آنے کا رسیدی ٹکٹ چسپاں کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔جسے منیر نیازی ریڈیو والوں کی سازش گردانتے تھے اور فرماتے تھے کہ انہوں نے ہر چیک پر ایک سانپ بٹھا رکھا ہے جسے دو آنے کا دودھ نذر کیے بغیر خزانے کا دروازہ وا نہیں کر سکتے۔
میرے پہلے ریڈیو پروگرام کے میزبان پروفیسر قیوم نظر تھے۔پروگرام سے پہلے انہوں نے کینٹن پر سب کی غزلیں دیکھیں تاکہ کوئی بے وزن یا بے اوسان شعر لاسلکی طور پر سامعین کے اذہان پر بوجھ نہ بنے۔اسی رو میں اپنی کئی غزلیں سُنائیں۔ایک شعر اب بھی میری یاداشت کا حصہ ہے:
دل توڑ کے جانے والے سُن، دو رشتے اب بھی باقی ہیں
اک سانس کی ڈور نہیں ٹوٹی،اک پریم کا بندھن رہتا ہے
اس نشست میں میں نے اپنی غزل”سنگیت سُریلے کیوں اتنے”سامعین کی نذر کی۔یہ غزل اس سے پہلے”نیا دور”میں چھپ چکی تھی مگر اب تک چُھپی ہوئی تھی۔ریڈیو پر پڑھ کر گاؤں آیا تو یہ عین اس وقت نشر کی گئی جب میرے ابّا جی وقت گزاری کے لیے ریڈیو سُن رہے تھے۔یہ غزل نشر ہونی شروع ہوئی تو مَیں جوتے پڑنےکے خوف سے کھسک لیا مگر انہوں نے ملازم بھیج کر طلب کر لیا اور کچھ اس طرح کا مکالمہ ہوا:
ابّا جی: یہ شاعری جو میں نے ابھی ریڈیو پر سُنی،تم نے کی ہے؟
میں: جی
ابّا جی: انسان کی کوئی ذات نہیں
پھر دیس قبیلے کیوں اتنے
تمہارا شعر ہے؟
میں:جی ہاں
ابّا جی:چنگا اے،چنگا اے۔یار تُوں شعر شُور آکھ لیا کر۔
اس کے بعد بقولِ میاں وارث شاہ”پاڑا کُھل گیا”اور میں نے شاعری کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔
یونیورسٹی میگزین کے میزبانوں میں جناب عارف عبدالمتین اور امجد اسلام امجد بھی تھے۔اسی پروگرام میں ہم سرّاج منیر سے متعارف ہوئے مگر اس کی روداد آگے چل کر۔
پاک ٹی ہاؤس میں اسرار زیدی صاحب سے روز کی ملاقات تھی۔وہ مجید امجد،فیض احمد فیض،منیر نیازی اور ظفر اقبال سے اپنی نسبت کے حوالے سے گُفتگُو کرتے تھے تو ہم اس کی صداقت پر کم ہی ایمان لاتے تھے مگر کسی رسالے میں ان کی ایک تصویر دکھائی دی،جس میں وہ کرسی نشین تھے اور فیض اور مجید امجد ان کے دائیں بائیں ایستادہ تو ان کے کہے پر یقین آیا۔شاید اس بدگمانی کی وجہ ان کی طبیعت کی سادگی تھی۔ٹی ہاؤس کی میز پر ہر کہ و مہ کے ساتھ بے تکلف نشست۔سادہ چائے کے دور۔عمومی زندگی سے جڑی حقیقت پسند گفتگو۔بناوٹ اور احساس ِعظمت سے نفور۔روز گھر واپسی پر سادہ روٹیوں کا پارسل ہمراہ۔سچ یہ ہے کہ یہ سب کچھ انہیں عام بنانے پر تُلا تھا اور جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی تو ہم بھی خالد احمد کی طرح ان کی پُوجا کرنے لگے۔ان کا کمال یہ تھا کہ وہ پھر بھی عام آدمی ہی رہے اور دھنی رام روڈ سے پاک ٹی ہاؤس کے درمیان ایک پاکیزہ روح کی طرح تیرتے پھرے۔
نئے شاعروں میں جاوید شاہین (زخم ِمسلسل کی ہری شاخ)،سلیم شاہد(صبحِ سفر)اور نذیر قیصر (آنکھیں،چہرہ،ہاتھ)کو پڑھ بھی لیا تھا اور ملاقات بھی رہنے لگی تھی۔ظفر اقبال کی”اب ِرواں”کا بہت شہرہ تھا مگر اس وقت کوشش کے باوجود دستیاب نہیں ہو پائی۔”فنون”کے غزل نمبر میں ان کی ہزلیہ شاعری کا تاثر کچھ اچھا نہیں تھا۔ادبی پرچوں میں بھی وہ اپنے آپ کو غیر سنجیدہ ثابت کرنے پر تُلے تھے اور تو اور انہوں نے”سویرا”کا ایک شمارہ مرتب کیا تب بھی اپنے امیج کو بہتر بنانے کی ضرورت نہیں سمجھی تو ہم نے بھی انہیں جُوں کا تُوں قبول کر لیا۔
یہی وقت ملک بھر کے نوجوان شعراء سے متعارف ہونے کا تھا۔غلام محمد قاصر،شبیر شاہد،محمد خالد،ثروت حسین،صابر ظفر،جمال احسانی،سلیم کوثر،پروین شاکر،شاہدہ حسن،صغیر ملال،ایوب خاور،خالد اقبال یاسر،اصغر ندیم سید،طارق جامی،محمد اظہار الحق،روحی کنجاہی،زمان کنجاہی،یوسف حسن،نجیب احمد سرمد صہبائی،ناصر بلوچ،رمضان شاہد،مشتاق صوفی،اختر کاظمی،اختر ہاشمی،لطیف ساحل،اعزاز احمد آذر ،عبدالستار سید،گلزار بخاری اور بہت سے نئے لکھنے والوں ہمارے حلقۂ احباب میں داخل ہوئے اور بہت سوں سے ایک طویل نسبت کی بنیاد پڑی جو آگے چل کر تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔
احباب میں اردو اور پنجابی سے جڑے احباب کی کثرت کا سبب یہ تھا کہ ہم خود دونوں زبانوں میں اظہار کر رہے تھے اور چھپ بھی رہے تھے۔یہ اس لیے کہ ہمارے تخلیقی کُل کو اس کے بغیر ظاہر کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔صرف اردو لکھتے تو محسوس ہوتا جیسے ابھی کچھ کہنا باقی ہے۔یہی کیفیت صرف پنجابی میں لکھنے میں تھی۔شاید ہماری زندگی کی دوہری شباہت دو زبانوں کا لبادہ چاہتی تھی سو ہم نے اِسے آج تک یہ سہولت فراہم کر رکھی ہے اور سچ یہ ہے کہ خاصے سُکھی ہیں۔
اس عرصے میں گاؤں پلٹے تو والد صاحب نے ایک طرح کا مدارالمہام بنا دیا۔غلہ منڈی کے معاملات ہمارے سپرد ہوئے۔حاجی محمد جرولہ،ریاض حسین قریشی،مہر منظور/مہر غلام محمد سنپال،راج محمد پاندہ،الیاس بھٹی،مہر صادق سنپال کی آڑھت کے علاوہ خود ہمارے بھائی مہر نواب اور تایا زاد مہر محمد نے بھی یہ شغل اختیار کر رکھا تھا۔جہاں کسی کو کسی کام کی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ابّا جی کے چیک ہم بچپن سے لکھتے آئے تھے اب کیش بھی کرانے لگے تھے۔منڈی سے بھی وصولی کا حق مل گیا تھا۔اس لیے جیب اور نیّت بھری رہتی تھی۔
یہی دن تھے جب لاہور سے یونیورسٹی میں داخلہ فارم جمع کرانے کے لیے بُلاوا آیا اور میں ماں سے معقول رقم اینٹھ کر نواز کے پاس جا پہنچا۔
درس گاہ – 49
کریسنٹ ہاسٹل میں دو برس اور سمن آباد میں چند ماہ کا یہ قیام عجیب رس بھرا تھا۔اب سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ لاہور میں قحط نہ پڑنے کے باوجود مَیں عشق فراموشی پر عمل پیرا رہا۔کبھی بھول کر بھی کوچۂ جاناں کا رُخ نہیں کِیا حالاں کہ فاصلہ چند فرسنگ سے زیادہ کا نہیں تھا۔سلیم شاد سے ملا نہ اُس گلی کے کسی اور مکین سے۔شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ حاکم علی رضا اور نذر حسین کاٹھیا گاؤں پلٹ گئے تھے۔ایک دیوانہ ہو کر اور دوسرا کچھ کچھ دیوداس کا مرکزی کردار بن کر۔مجھے پُرانے دوستوں کے ساتھ نئے دوست میسّر آ گئے تھے۔عبدالوحید رشی نے میرے بکھراؤ کی تہذیب کر دی تھی۔کرشن چندر کی دو فرلانگ لمبی سڑک کو ناپنا میرا معمول تھا،جسے عرف ِعام میں کچہری روڈ کہتے ہیں۔گورنمنٹ کالج کے سامنے سے گزر کر گوشۂ ادب پر رسائل کی ورق گردانی،نسیم بک ڈپو اور آئیڈیل بک سٹور ٹولنٹن مارکیٹ،کلاسیک اور فیروز سنز مال روڈ سے کتابوں اور ادبی رسائل کی خریداری،پاک ٹی ہاؤس میں اسرار زیدی صاحب کی صحبت میں اپنے ہم عصر نوجوانوں سے روز کی ملاقات۔سعادت سعید،مستنصر حسین تارڑ،عطا الحق قاسمی،علی اکبر عباس،خالد احمد،شبیر شاہد،حسن رضوی،اجمل نیازی سے بتدریج قربت اور دھیرے دھیرے پہلی میز کے نابغوں سے تعارف،جن میں سلیم شاہد،جاوید شاہین اور احمد مشاق شامل تھے اور ادبی رسائل میں مجھے ایک خاص استقامت اور سرعت سے نمود کرتا دیکھ کر محبّت سے ملتے تھے اور ان سب کے علاوہ جنابِ شہرت بخاری اور ان کے توسط سے انجم رومانی،منیر نیازی،انتظار حسین اور زاہد ڈار سے تعارف کی سعادت۔غرض مجھے ہر میز پر قبول کیا جا رہا تھا مگر میری خلقی جھجھک ابھی دور نہیں ہوئی تھی۔میں نے کبھی شعر سُنانے کی ہمّت کی نہ ہی حلقے کے اجلاس میں اپنی کوئی تحریر تنقید کے لیے پیش کی۔بس میری حیثیت ایک سامع کی تھی اور میں اسی پر قانع تھا۔ہاں مجھے ادبی رسائل سے بذریعہ خط کتابت معاملہ کرنے میں کوئی عار نہیں تھا اور یہ نسبت بڑھ رہی تھی۔اس قدر کہ دو برس ہی میں مَیں’سویرا،فنون اور’نقوش’کے سوا ہر قابلِ ذکر پرچے میں چھپ چکا تھا اور ان رسائل کے توسط سے ملک بھرکے اپنے ہم عصر اہم شاعروں سے بھی متعارف ہو چکا تھا،جو آگے چل کر میرے گہرے دوست بننے والے تھے۔
اس دوران میں اسلامیہ کالج،انجینرنگ یونیورسٹی،پنجاب یونیورسٹی اور شہر کے کئی مشاعرے پڑھے اور اپنے کالج میں اپنی زندگی کا پہلا آٹو گراف دینے کی عزت بھی ملی۔اب مجھے’فاران’میں بھی چھاپ دیا گیا تھا۔بس فرق تھا تو یہ کہ کہیں سالِ چہارم درج تھا تو کہیں پنجم اور کہیں سابق طالب علم۔میرے مزاحیہ مضامین’زعفران’اور’فانوس’میں چھپے تھے اور ان سب سے میاں چنوں پلٹ کر بھی ویسا ہی پُر لطف رابطہ بحال رہا۔علی ظہیر منہاس کے ٹھکانے پر جانا بھی معمول میں شامل تھا۔میں’افکار’کا مصطفیٰ زیدی نمبر پڑھ چکا تھا مگر اُن سے اصل تعارف ظہیر کے ذریعے ہی ہوا جو اُن کے کرشمے کے اسیر تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ انہیں آئیڈلائزڈ کرتے تھے۔اُن کے اچھا شاعر ہونے میں کوئی شُبہ نہیں مگر وہ میرے مزاج کو راس نہیں تھے،اس لیے ان کی چھاپ ظہیر کی شاعری تک محدود رہی۔وہیں ایک کمرے میں’اوراق’کا دفتر تھا۔اس سے مجھے یہ آسانی تھی کہ تازہ شمارہ فوراً ہی اعزازی حیثیت میں پہنچ جاتا تھا۔
پاک ٹی ہاؤس میں جناب عارف عبدالمتین سے تعارف ہوا تو انہوں نے گھر آنے کی دعوت دی۔میں اس عنایت کی توقّع نہیں رکھتا تھا مگر اُن کے لہجے میں ایسا خلوص اور محبّت تھی کہ اگلے ہی روز اُن کے ہاں جا پہنچا۔وہ سیکرٹریٹ کے پیچھے چشتیہ ہائی سکول کی بغل میں رہتے تھے۔میرے حاضر ہونے پر انہوں نے بڑی کُشادہ دلی سے استقبال کیا۔اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اپنے بچّوں سے ملایا۔یہ خاندان جمال اور حُسنِ اخلاق کا مرقع تھا۔میں بیسیوں بار ان کے یہاں حاضر ہوا۔اپنی شاعری سُنائی۔کج بحثی کی۔یہ زمانہ تھا جب مجھ پر دہریہ نظریات غالب آ رہے تھے اور اس کی جھلک میری شاعری میں بھی دکھائی دینے لگی تھی مگر عارف صاحب نے بہت دھیمے لہجے میں میری اصلاح کی اور مجھے بھٹکنے نہیں دیا۔انہوں نے میری فکر اور ترقّی پسندی کو کبھی ہدف نہیں بنایا مگر میرے ہدف کے تعین میں میری رہنمائی ضرور کی۔مجھے اب کتابیں جمع کرنے کا شوق چرایا تھا اور میں بلا توقف ہر اچھی کتاب خرید لیتا تھا۔عارف صاحب کی کئی کتابیں میں نے اسی رو میں خریدیں۔آپ نے اپنی نئی کتب عنایت بھی کیں۔بیسیوں غزلیں اور نظمیں اُن کی زبان سے سُننے کا موقع ملا مگر میرے مزاج کی کجی کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی میرے پسندیدہ شعرا میں شامل نہیں ہو پائے تاہم اُن کی ذات اور خاندان کے لیے میرے دل میں موجود احترام میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔میں نے اُن سے بڑھ کر نسل ِنو سے محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔اُن کا خمیر گِل ِخیر سے اُٹھایا گیا تھا۔وہ جتنے شیریں سُخن اور نرم دمِ گفتگو تھے۔میرے جاننے والوں میں ایسی کوئی اور مثال موجود نہیں۔
عارف صاحب کے ہاں ایک بار ڈاکٹر وزیر آغا سے ملاقات ہوئی۔وہ میری کوئی غزل’اوراق’میں شائع کرنے سے پہلے ایک خط لکھ کر اطلاع دیتے تھے اور میں نے اُن کی متعدد کتب پڑھ رکھی تھیں۔اس لیے اُنہوں نے شفقت کی اور اپنے لاہور میں موجود ہونے کی صورت میں ملتے رہنے کی دعوت دی مگر میں اس دعوت کا فائدہ نہیں اُٹھا سکا۔شاید اس کی وجہ کاہلی اور میری کُھردری انا تھی۔عجیب بات تھی کہ دیہات سے نسبت اور زمیندارانہ پس منظر رکھنے والے ادیب مجھے اپنی طرف کھینچتے بھی تھے اور میں اُن کے قریب ہونے سے کتراتا بھی تھا۔آغا صاحب اسی زُمرے میں آتے تھے۔سو ان سے اُس دور میں دو ایک ملاقاتیں(وہ بھی عارف صاحب کے بُلاوے ہر) سلاطین مال روڈ پر ہوئیں۔جس میں اُنہوں نے تواضع کا حق ادا کر دیا۔یہی ریستوراں بعد میں گارڈنیا کہلایا اور پھر وہاں وین گارڈ بکس نے ڈیرا جما لیا۔ہاں آغا صاحب سے تجدید ِتعلق کا ایک دور ملتان سے لاہور واپسی پر آغاز ہوا،جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔
اس بار گاؤں گیا تو خادم رزمی صاحب اور ساغر مشہدی سے روز ملنے چلا جاتا۔کبھی وہ میرے مہمان ہوتے اور کئی بار میرے کسی اور دوست کے یہاں نشست جمتی۔خان غضنفر روہتکی سے ملاقات بھی معمول میں شامل تھی۔کبھی میں اور رزمی صاحب کبیر والا کا چکر بھی لگا آتے تھے۔شمیم اکبر آبادی کے تکے کباب بھی اُڑائے جاتے۔رزمی صاحب کے بقول یہ میری پرواز کا آغاز تھا اور شاید وہ غلط نہیں تھے۔میں ملک بھر کے ادبی رسائل میں چھپ رہا تھا اور میرے حلقۂ احباب میں تیزی سے وسعت آ رہی تھی۔میرے علاقے کے کئی لکھنے والے میری وجہ سے ادبی رسائل تک رسائی پا رہے تھے اور اپنی ذات پر میرا اعتماد بڑھ رہا تھا۔
اسی دوران میں بی۔اے کا رزلٹ آ گیا۔مجھے پاس ہونے کی توقّع تھی مگر بنگلہ دیش نامنظور تحریک سے معطل ہونے والی تعلیمی سرگرمیوں کا کچھ اثر تو ہونا ہی تھا۔انگریزی،پولیٹکل سائنس اور فارسی میں میرے نمبر بہت اچھے تھے مگر اکنامکس کے دوسرے پرچے یعنی پاکستان اکنامکس میں کمپارٹمنٹ تھی اور میری مشکل یہ تھی کہ میں ایم۔اے میں اکنامکس ہی پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔صدمہ تو ہوا مگر یہ جان کر اطمینان ہوا کہ اکثریت کا یہی حال ہے اور ایم۔اے کے داخلے اگلے امتحان کے بعد ہوں گے۔کیوں کہ اس امتحان میں بہت کم لوگ بیٹھے تھے اور شاید نئی کلاسز شروع کرنے کے لیے طلبہ کی مطلوبہ تعداد کا دستیاب ہونا ممکن نہ تھا۔اب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ پاکستان اکنامکس کے پیپر کی تیاری کہاں کی جائے۔اگر مجھے لاہور رہنا ہے تو کہاں رہوں؟ اور لاہور رہنا ضروری تھا۔اس لیے کہ گاؤں پلٹ کر اس پرچے کے امتحان کی تیاری کرنا ممکن نہیں تھی۔سو وہ رات میں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج ہاسٹل میں نواز طاہر اور شبیر احمد اختر کے ساتھ گزاری۔اُن سے اپنے مستقبل کے بارے میں مشورہ کیا اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یونیورسٹی اورینٹل کالج کے بعض شعبوں میں ایم۔اے کے داخلے ہو رہے ہیں۔ان مضامین میں اردو اور پنجابی شامل تھے۔نواز طاہر اب پنجابی کے طالب علم تھے۔اُن کے اصرار پر میں نے اردو اور پنجابی دونوں میں داخلے کے لیے درخواست صرف یہ سوچ کر دینے پر رضامندی ظاہر کی کہ داخلہ ہو جانے کی صورت میں مجھے ہاسٹل مل جائے گا اور میری لاہور میں رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔میں اپنے والد کے کسی مہرباں کے ہاں ٹھہر سکتا تھا مگر میرا دل کسی زمیندار کے ہاں ٹھہرنے پر راضی نہیں تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میرے ابّاجی میرے اس فیصلے پر معترض نہیں ہوں گے۔
معلوم نہیں میرے مزاج میں یہ ٹیڑھ کہاں سے آئی تھی مگر میں کچھ عجیب سا،پہلے سے کچھ الگ ہوتا جا رہا تھا۔اُس زمانے میں لاہور فورٹریس اسٹیڈیم میں عوامی میلہ منعقد کیا جاتا تھا،جس کے شالیمار ایونیو کو وی آئی پی گردانا جاتا تھا اور اس کا ٹکٹ پانچ سو روپے کا تھا مگر اس میں ایک آپشن یہ تھا کہ کسی بھی ایم پی اے(ممبر پنجاب اسمبلی)سے اس کے پاس مل جاتے تھے۔میں یہ پاس حاصل کر کے میلہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ہمارے علاقے کی سیٹ پر محمد خان خاکوانی اور میاں چنوں شہر کی سیٹ پر ڈاکٹر صادق ملہی کامیاب ہوئے تھے۔دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور دونوں سے قربت تھی۔ایک بار حق نواز اور دو ایک اور عزیزوں کی میلہ دیکھنے کی غرض سے آمد پر پاس لینے پیپلز ہاؤس گیا تو خاکوانی صاحب اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔اُن کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔میں سیڑھیاں اُتر رہا تھا کہ ڈاکٹر صادق ملہی مل گئے۔ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے اور آنے کی وجہ پوچھی۔میں نے بتایا کہ خاکوانی صاحب سے میلے کے پاس لینے آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے لے جاؤ۔پتا نہیں میرے من میں کیا آئی کہ میں نے شکریے کے ساتھ معذرت کر لی اور کہا کہ دوبارہ آ کر خاکوانی صاحب ہی سے لے لوں گا۔اب کون بتائے کہ اس جواب میں کیا منطق تھی اور ایک مہربان کو حق دق چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟
نواز کو داخلہ شروع ہونے کی اطلاع کرنے کا کہہ کر میں ایک بار پھر گاؤں پلٹ آیا۔شاعری اور شکار دونوں دوبارہ جاری ہوئے۔رزمی صاحب سے اب دوستی اور بے تکلفی بڑھ گئی تھی،جس کی وجہ سے منیر ابنِ رزمی کو بزرگ بھتیجے کا درجہ تفویض ہوا اور ان کے چھوٹے بھائی کو ننّھے کا مگر اس ننھّے کو’الف نون’سے کوئی نسبت نہیں تھی۔رزمی صاحب کی اولاد بڑی لائق فائق،طلبہ سیاست میں بہت فعال اور شیریں مقال تھی۔یہ کام ہمارے بس کا نہیں تھا۔ہم بس قلم کے دھنی تھے اور شاید یہ دعویٰ تب بھی غلط تھا اور اب بھی درست نہیں۔
درس گاہ – 48
میاں چنوں قیام ہی کے دوران میں’نئی قدریں’حیدر آباد (سندھ)کے مدیر استاد اختر انصاری اکبر آبادی نے اطلاع دی کہ وہ اپنے سالانہ دورے پر پنجاب تشریف لا رہے ہیں اور میاں چنوں رُک کر مجھے بھی شرف ِملاقات بخشیں گے۔یہ خبر میرے لیے مسرّت اور تقویت کا باعث تھی۔کیوں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی ادبی رسالے کا مدیر مجھ ایسے معمولی آدمی سے بھی ملاقات کا متمنی ہو سکتا ہے۔میں نے اپنے احباب کو ان کی آمد کی اطلاع دی اور انہیں خود تانگہ چلا کر اسٹیشن سے گھر لانے کے لیے نکلا۔وہ خیبر میل سے پہنچے جو اُس زمانے میں ڈیڑھ بجے میاں چنوں قدم رنجہ فرماتی تھی اور میں انہیں لے کر گورداسپور سویٹ ہاؤس پر رُکا،جہاں ان کی مفرحات سے تواضع کی۔وہاں انہوں نے سگریٹ خرید کر دینے کی فرمائش کی اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے ان کے اس مطالبے سے معمولی سا صدمہ پہنچا۔شاید اس کی وجہ ان کا بلند مرتبت ہونا اور میرا تمباکو نوشی سے نابلد ہونا تھا۔خیر میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے گولڈلیف کی ایک ڈبیہ اور ماچس خریدی اور فخر سے بھرا ہوا گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔میری اکٹر کا عالم یہ تھا کہ بازار میں راستہ مانگنے کو پیتل کی گھنٹی پر پاؤں رکھتا تھا تو اٹھانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ایک بار تو کسی صاحب کے احتجاجی منہ بنانے پر باقاعدہ بدمعاشی دکھانے کو چابک لے کر اُتر گیا اور مہمان کی مداخلت پر ہی ٹلا۔وہی کیڑی کے گھر نارائن آنے کی کیفیت تھی اور میں آپے میں سما نہیں پا رہا تھا۔وہ وضع قطع اور لباس میں کچھ کچھ نارائن کی شباہت بھی رکھتے تھے اور جگت استاد کے درجے پر فائز تھے۔برسوں بعد میں نے پروفیسر سجاد باقر رضوی سمیت بیسیوں اکابرین کو انہیں استاد کہہ کر مخاطب کرتے دیکھا تو یقین آیا کہ استادی بھی ایک خدائی عطا ہے جو ہر ایک ذات پر زیبا نہیں دیتی اور(شاید)جوش ملیح آبادی کے یہ اشعار بلا شبہ مبنی بر شقاوت ہیں:
اس تیرے تخلص میں کیا چیز ہے بنیادی
اختر ہے کہ انصاری ، اکبر ہے کہ آبادی
مُلک جب ہوا تقسیم آیا اپنے حصّے میں
ایک اختر انصاری ، وہ بھی اکبر آبادی
خیر میں انہیں لے کر بستی تک اینڈتا آیا۔میرے دوستوں میں خادم رزمی،ساغر مشہدی،سجاد پاندھا،فلک شیر سنپال،اصغر علی شاہ کھگہ وغیرہ پہلے سے بیٹھک میں موجود تھے۔دیسی مرغ اور بٹیرے پکے تھے۔ساتھ لسّی،اچار،چٹنیاں،سلاد اور تندوری روٹی جسے تفتان کہنا مناسب ہوگا۔کھانا سب نے رغبت سے کھایا مگر مسئلہ تب ہوا جب استاد کو واش روم کی حاجت ہوئی۔یہاں اس کا کچھ رواج نہیں تھا۔سب نظام یہاں ضابطے میں بندھا تھا۔علی الصباح کھیتوں کا رُخ کرنا اور موسم کے اعتبار سے اندھیرے اور فصلوں کو چادر بنانا معمول تھا۔اس طرح کہ اُن پر جمال احسانی کا شعر صادق آتا تھا:
صبح ہوتے ہی نظر آتے ہیں جو کچھ لوگ یہاں
یہ سحر خیز ہیں یا رات کے جاگے ہوئے ہیں؟
اب استاد کے اس ناوقت مطالبے کا حل یہی تھا کہ انہیں خالص تانبے کا منقش آفتابہ تازہ جل سے بھر کر تھمایا اور اشارے سے لکڑی کی پُلیا پار کر کے کھیتوں میں سر چھپانے کی صلاح دے کر روانہ کیا مگر وہ ایک حویلی کی ڈیوڑھی میں جا چھپے۔وہ تو خیریت گُزری کہ معاملہ نچلے درجے کا نہیں تھا اور صاحب ِخانہ کو اس ایجاد کی خبر نہیں ہوئی۔استاد کامیاب اور زندہ پلٹ آئے ورنہ’نئی قدریں’ کے مدیر اُس رات کی گاڑی سے لاہور نہیں پہنچ پاتے اور ہمارے گاؤں میں بھی پختون بھائیوں کی لُطفیہ روایت کے تتبع میں’مہمان کُشی’واجب ٹھہرتی۔
استاد کا اصل مقصد رسالے کے لیے سالانہ خریدار تلاش کرنا تھا۔یہاں یہ مقصد آسانی سے پورا ہوا۔میرے کہنے پر ہر ایک نے خریداری لی اور خود میں نے پانچ دوستوں کے لیے جاری کرایا۔ان سب کو ایک ایک پرچہ نذر کیا گیا۔پھر استاد نے اسے جاری رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور ان خریداروں کو اس کی طلب بھی نہیں تھی مگر اس سے یہ فائدہ ہوا کہ استاد نے اپنی کتاب’مضامین’میں اس حقیر کی غزل کو بھی حوالہ بنایا اور ہمیں’نئی قدریں’میں من مانی کرنے کی اجازت مل گئی۔
لاہور پلٹ کر ہم ایک بار پھر ہاسٹل میں جم گئے۔میں اور میرے سبھی دوست پلٹ آئے تھے مگر ہاسٹل کچھ غیر آباد سا تھا۔اس لیے میس شروع نہیں ہو سکا اور ہم ناصر باغ کے راستے پُرانی انارکلی آ کر دوپہر اور رات کا کھانا کھاتے رہے۔اس معمول کے دوران میں ایک بار عدیم ہاشمی کو جو ایک شاعرہ کے ساتھ دمدمہ توپ کے پاس کہیں جا رہے تھے اور کسی راہگیری ٹولی کے نازیبا ریمارک سے برافروختہ ہو کر اُن کے گلے پڑ گئے تھے،پٹنے سے بچانے کی سعادت حاصل کی مگر اس سے اہم بات یہی تھی کہ ہم بیس فیصد کے لگ بھگ لوگوں نے گریجویشن کا یہ امتحان دیا۔حالاں کہ فورتھ ائیر کا کورس پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔پارٹ ٹو کے سبھی پیپر اللہ توکلی تھے۔کوئی مہینے بھر میں یہ کام نبیڑ کر میں شکور احمد خالد کے پاس سمن آباد مین روڈ پر ایک کھنڈر نما عمارت میں منتقل ہو گیا۔یہ’گھر’معروف لوک گلوکار عالم لُہار نے کرایے پر لے رکھا تھا۔سڑک کے رُخ پر کھلنے والے ایک کمرے میں اُن کا دفتر تھا۔وہ’مٹّی دا باوا’نامی ایک فلم بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور زرتاش نامی ایک صاحب ان کے فلم ڈائریکٹر تھے۔میرے اور شکور کے پاس پچھلے صحن میں کھلنے والا ایک عمدہ کمرہ تھا مگر یہاں ٹائلٹ کی سہولت تو تھی،غسل خانے کی نہیں سو اور بھی کئی اہلِ محلہ کی طرح ہم بھی معصوم شاہ قبرستان کی مسجد کے غسل خانوں کا فائدہ اٹھاتے تھے۔جس کی دوسری طرف جنک نگر کا ایک ٹکڑا تھا۔
یہاں میں نے بے وجہ تین ماہ گزارے۔کھانا سمن آباد موڑ کے ایک ہوٹل پر کھایا جاتا۔شام کو بس یا وین پکڑ کر ٹی ہاؤس چلا جاتا۔اکثر رات کا کھانا وہیں کھا کر پلٹتا۔سردیوں میں کمرے میں اور گرمیوں میں سروس روڈ پر چارپائیاں ڈال کر سوتے۔بالکل مقابل میں اداکارہ شمیم آرا کا گھر تھا۔جہاں گردشی کاتب’بوتل نگر’کا دیواری طغرہ ٹانک جاتے تھے۔شکور صاحب اداکارہ سنگیتا کی بہن جو مستقبل میں کویتا بننے والی تھی،کو ٹیوشن پڑھا رہےتھے۔دلچسپ صورت تب پیدا ہوتی جب گھر لوٹنے پر ہماری چارپائی کسی اداکارہ کے قبضے میں ہوتی۔واگزاری کی صورت پیدا نہ ہو پاتی تو درمیان میں کتابِ صبر رکھ کر رات کاٹنا ہڑتی مگر رات کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ بالآخر کٹ جاتی ہے۔
ان میں سے کچھ نام ور بھی ہوئیں۔دو تین ماہ بعد میں اس سارے بندوبست سے اُکتا گیا اور رزلٹ آنے تک گاؤں پلٹ آیا۔اب کی بار میاں چنوں کی بجائے تلمبہ کا رُخ کیا اور شاعری کے سوا کوئی مصروفیت نہیں پالی۔یہی وہ زمانہ ہے جب مجھے لگا کہ میں شاعر ہوں اور مجھے اپنی اس حیثیت کو اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں اظہار کا وسیلہ بنانا ہے۔
درس گاہ – 47
میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ بنگلہ دیش نامنظور تحریک کی افادیت کیا تھی اور اس سےسرکاری اور پرائیوٹ املاک کی بربادی کے سوا کیا حاصل ہوا؟کیا ہمارے نامنظور کرنے سے بنگلہ دیش پلٹ کر مشرقی پاکستان بن جاتا؟ میں شاید کُند ذہن ہوں کہ بعض حکومتی اقدامات میری فہم سے ورا رہتے ہیں مثلاً ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جب کہ اس کے قریبی ہمسائے اُسے تسلیم کر چکے۔چلیں اس میں کوئی مصلحت ہو گی مگر بنگلہ دیش کے سلسلے میں ایک تاریخی صداقت کو جھٹلا کر ہم کیا مفاد حاصل کر رہے تھے اور پیہم گھیراؤ جلاؤ کے عمل سے عام شہری کو کیا پیغام دے رہے تھے؟اقبال نے کہا تھا’جُدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی”مگر یہاں ہمیں معکوس صورتِ حال کا سامنا تھا اور اس کا خمیازہ ان طالب علموں نے بُھگتا جو حصولِ علم کی کوشش میں سنجیدہ تھے۔
گاؤں پلٹنے کے بعد لاہور کے پُرسکون ہونے کی خبر ملنے تک مجھے کوئی خاص کام سوائے گھومنے اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے تھا ہی نہیں۔اس دوران میں طالب حسین کی ضد پر ابّاجی نے ایک بائیک یاماہا100سی سی خرید دی تھی۔حق نواز کے پاس شیل کی ہیوی بائیک تھی اور میرے ایک اور دوست کے پاس ٹرامف سو کبھی میاں چنوں،کبھی تلمبہ اور کبھی ہٹھاڑ کی دھول پھانکی جاتی۔خادم رزمی اور ساغر مشہدی کے ساتھ نششت جمتی،جس میں مائی صفورہ سے صاحب زادہ ارشاد قمر بھی آ شامل ہوتے۔کبھی میاں چنوں میں گِل ورائٹی سٹور پر چلا جاتا جو جمیل اقبال گِل نے قائم کیا تھا اور وکالت کرنے کے ارادے سے تائب ہو کر اپنے آبائی پیشے سے مناکحت کر لی تھی۔یہی سٹور میری ڈاک کا ٹھکانہ بھی تھا۔ساغر مشہدی نے تلمبہ رزمی صاحب کے سکول کے قریب تیس روپے ماہانہ پر ایک دکان کرایہ پر لے کر حکمت کی دکان کھول لی تھی مگر اس میں مریضوں کی بجائے شاعروں کا جمگھٹ لگا رہتا تھا۔خان غضنفر روہتکی کی دکان کا پھیرا بھی روز کا معمول تھا اور وہ تازہ غزل اور کڑک چائے سے تواضع کرتے تھے۔
انہی دنوں شمیم اکبر آبادی سے ملاقات کی سُوجھی اور رزمی صاحب اور ساغر مشہدی کو میاں چنوں پہنچنے کا کہہ کر میں گل ورائٹی سٹور پر ان کا منتظر رہا۔شمیم صاحب اُس وقت میاں چنوں کی شعری روایت کے اکلوتے وارث تھے اور مین بازار میں تکہ کباب لگاتے تھے۔وہ کافی بڑی دکان پر قابض تھے مگر اندر کھانے کے کمرے پر کمرے سے زیادہ کسی متروک مندر کا گمان گزرتا تھا۔پہلی اور اس کے بعد ہر ملاقات کا اُصولی ضابطہ یہ ٹھہرا کہ ہم آتے ہی کباب روٹی کا آرڈر دیتے۔جب کھانا لگا دیا جاتا تو شمیم صاحب ہمارے پاس آ بیٹھتے اور مشاعرہ برپا کیا جاتا۔وہ توندیل تو نہیں تھے مگر ان میں اکبر آباد کی ساری خاصیتیں تھیں۔سانولا رنگ،مغلیہ سٹائل زلفیں گردن پر خم کھائی ہوئی،ہونٹ پان سے بھڑکے ہوئے،منجھلے قد اور ڈھیلے بدن پر پیٹ کا خم قدموں کی ذرا سرزنش کرتا ہوا۔بچپن سے میں انہیں اسی طرح دیکھتا آیا تھا کہ وہ اچھے گوشت کی خریداری کے لیے سویرے کوٹ سنجان سنگھ جانے کے لیے بس کے انتظار میں ٹی چوک پر کھڑے ملتے تھے مگر اس مندر میں اُن کی آرتی اتارنے کا آغاز اب ہوا تھا۔ہر بار کھانے کےبعد چائے اُن کی طرف سے پلائی جاتی اور وہ’شمیم ِخستہ تن’اور’شمیم ِزار’ کی لازمی بندش کے ساتھ مقطع تک رسائی پاتے۔حالاں کہ یہ دونوں صفات ان میں مفقود تھیں۔اس کھانے کا بل مَیں دیتا تھا اس لیے اُن کی نظر میں مَیں ساغر اور رزمی صاحب کے مقابلے میں بہتر شاعر تھا۔حالاں کہ رزمی صاحب کی جدت طرازی اور خلّاقی بِلا شُبہ بے مثل تھی اور اگر وہ زیادہ پڑھے ہوتے اور عالمی ادب سے لگاؤ رکھتے تو شاید ہی اس علاقے کا کوئی شخص ان کی تخلیقی صلاحیت کو چُھو پاتا۔یہی مسئلہ ساغر مشہدی کا بھی تھا۔اس پر وہ غزل سے معاملہ نہیں کر پا رہے تھے جب کہ مسدس کہنے میں وہ بہت سُبک دست اور مسُمّط نظم کی تعمیر کرنے میں خاصے مشّاق تھے۔
شمیم اکبر آبادی کی غزلیں کلاسیکی رنگ لیے ہوتی تھیں اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی مگر وہ روایت سے اس شدّت کے ساتھ جُڑے تھے کہ پامال مضامین کی جگالی پر اُتر آئے تھے۔قافیہ ردیف کے اختلاف کے باوجود ان کی ہر غزل اُن کی پہلی غزل کا پرتو ہوتی تھی اور لگتا تھا جیسے ان کی شاعری فکری الزائیمر کا شاخسانہ ہے۔خود میری حالت شاید اس سے مختلف نہیں تھی تاہم رزمی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں عمودی سفر میں ہوں اور تیزی سے اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں جب میں ایک طیّارے کی طرح فضا میں ہموار پرواز کے لائق ہو جاؤں گا۔معلوم نہیں اس میں کتنی سچّائی تھی مگر یہ ضرور تھا کہ ادبی پرچے مجھے خوش دلی سے چھاپ رہے تھے اور میں اپنے ہم عصر لکھنے والوں کے حلقے میں شناخت بنا رہا تھا۔
رزمی صاحب زُود گو تھے تو کم گو مَیں بھی نہیں تھا۔ہر ملاقات پر ہمارے پاس سُنانے کو بہت کچھ ہوتا تھا۔وہ اُن دنوں تلمبہ اور اس کے گردونواح کے شاعروں کے کلام پر مشتمل ایک انتخاب شائع کرنے کی فکر میں تھے۔اس کے لیے میرے سمیت سولہ شاعروں کا کلام یکجا کیا گیا اور مرتب کی حیثیت سے خان غضنفر روہتکی کا نام دیا گیا۔دیباچہ ملتان کے ایک ادیب شیر احمد خاموش کا تھا اور شعرا کے تعارفی شذرے رزمی صاحب کے قلم کی عطا تھے۔’تاروں کی بارات’ نام کا یہ انتخاب اتنی تاخیر سے اور اخباری کاغذ پر اتنا بُرا طبع ہوا کہ شاید ہی کسی شاعر نے اسے دل سے سراہا ہو۔میں نے اس انتخاب میں شامل کلام اپنی کسی کتاب کا حصہ نہیں بنایا مگر میرے فکری سفر کے محاکمے کے لیے اس کو سامنے رکھنا بہرطور سودمند ہو سکتا ہے۔
انہی جبری تعطیلات کے دوران میں ایک بار رزمی صاحب کی خواہش پر میں اور وہ بائیک پر کبیر والا جا کر بیدل حیدری صاحب سے ملے۔انہوں نے چائے پلائی اور کچھ عارفانہ گفتگو کے بعد،جس کے بیچ وہ بار بار اُٹھ کر اپنی دکان کے پردے کے پیچھے گم ہو جاتے تھے،اپنی کچھ غزلیں سُنائیں جو مجھے کچھ خاص خوش نہیں آئیں۔اس سے پہلے میں اور رزمی صاحب نے رسماً اپنا کلام سُنایا اور بیدل صاحب نے میرے حق میں کچھ ارشاد کیا جس کی تفصیل مجھے اب یاد نہیں۔میرے رنگ ِسخن سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر رزمی صاحب یا علاقے کے کسی اور شاعر کا اثر نہیں سو انہوں نے میری اصلاح کا عندیہ دیا نہ کلام کی سمت مقّرر کرنے کے حوالے سے کوئی بات کی۔ پہلے ہی روز ہمارے مابین ایک دوسرے کے فکری مکاشفوں کے حوالے سے قبولیت اور احترام کا رشتہ قائم ہو گیا اور اُن سے آخری ملاقات تک قائم رہا تب بھی جب وہ ڈاکٹر وزیر آغا کی عظمت کے حُدی خواں تھے اور تب بھی جب وہ احمد ندیم قاسمی کے پرستار ہوئے۔
ایک بار میں اور رزمی صاحب ملتان بھی گئے۔گورنمنٹ کالج میں مشاعرہ تھا۔ملتان اور گردونواح کے بہت سے شاعر موجود تھے مگر میں کسی کو کم ہی پہچانتا تھا۔ہاں ان کے نام اور کلام سے شناسائی ضرور تھی۔اس مشاعرے میں عابد عمیق نے اردو کی ایک بالغانہ نظم سُنائی تھی۔اصغر ندیم سیّد اور محمد امین بھی موجود تھے اور سینئیرز میں اصغر علی شاہ، اسلم انصاری،فرخ درانی،ارشد ملتانی، عاصی کرنالی، حسین سحر اور عرش صدیقی۔مجھے بھی اپنا کلام سُنانے کا موقع دیا گیا اور مشاعرے کے بعد کالج کینٹن پر محمد امین،اصغرندیم سیّد اور دوسرے دوستوں سے نشست رہی۔میرے لیے اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ میرے نام سے آگاہ تھے۔شام کو ہم ارشد ملتانی صاحب کے گھر پر ان سے ملے جو بوہڑ گیٹ کے کہیں آس پاس تھا۔وہ بھی بہت محبت سے ملے اور سب سے باہمی احترام اور دوستی کا ایک ایسا رشتہ قائم ہوا جو ہمیشہ برقرار رہنے والا تھا۔
مجھے تاروں کی بارات’کی دس کاپیاں عطا کی گئیں۔کچھ میں نے خریدی اور اپنے عزیز و اقارب کی نذر کیں۔تب کالج کُھلنے کی نوید پہنچی اور ہم دونوں بھائی لاہور پلٹ آئے۔اتنا وقت ضائع ہو گیا تھا کہ تعلیمی اداروں کا شیڈول برباد ہو کر رہ گیا تھا۔اس لیے گمان تھا کہ اس پر نظر ِثانی کی جائے گی مگر پنجاب یونیورسٹی نے وقت پر امتحان لینے کا اعلان کر کے سب کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔طلبہ امتحان کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے مگر اربابِ اختیار تھے کہ ان کے کانوں پر جُوں تک نہیں رینگ رہی تھی سو جب کالج میں امتحانی داخلہ بھجوانے کا نوٹس لگایا گیا تو مَیں نے داخلہ بھجوانے ہی میں عافیت جانی۔
درس گاہ – 46
شہرت بخاری صاحب سے یہ مکالمہ تعلّی کے زُمرے میں آتا تھا مگر اس کے پیچھے کہیں اپنی ذات اور ہنر پر اندھا اعتماد تھا اور یہ اعتماد تلمبے کے دوستوں کا عطا کردہ تھا۔میرے بھیتر میں کہیں آگ کی کوئی لپک تھی جو اب میرے قد کے برابر ہو رہی تھی اور میں زیادہ تر وقت خود اپنے ساتھ گزارنے لگا تھا۔
شہرت صاحب نے اب مجھے میری تمام ترحماقتوں کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔مجھے جب فرصت ہوتی میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا اور وہ مجھے اپنے ملاقاتیوں سے بھی ملاتے۔ان کے ممدوحین کی اکثریت شاعروں اور ادبی پرچوں کے مدیران کی تھی۔ان میں سے کچھ اس کالج کے پُرانے طالب علم تھے.شہرت صاحب ایسے کسی فرد کی فاران میں کوئی تحریر شامل کرتے وقت اس کے نام کے ساتھ سابق طالب علم کا لاحقہ ضرور چسپاں کرتے اور ایک بار یہ اعزاز مجھے بھی ملا۔
ان دنوں وہ پاک ٹی ہاؤس میں حلقہ اربابِ ذوق (ادبی) چلا رہے تھے
انہوں نے مجھے وہاں آنے کی دعوت دی اور میں علی ظہیر منہاس کے ساتھ وہاں جا پہنچا۔اس سہارے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میں ادبی رسائل میں شائع ہونے کے باوجود لاہور کے کسی شاعر یا ادیب سے بے تکلف تھا نہ لکھنے والوں کی اس بہشت میں داخل ہونے کی ہمت رکھتا تھا۔ہم پاک ٹی ہاؤس میں داخل ہوئے تو شہرت صاحب سامنے کی میز پر انتظارحسین،انجم رومانی،زاہد ڈار،سجّاد باقر رضوی اور احمد مشتاق کے ساتھ بیٹھے تھے۔دائیں طرف سلیم شاہد اور جاوید شاہین اپنے دوستوں کے ساتھ براجمان تھے اور سیڑھیوں کے بغلی سوفے پر اسرار زیدی اور سیف زلفی۔علی ظہیر منہاس غالباً سیف زلفی سے متعارف تھے سو ہم وہاں جا بیٹھے اور مدتوں بیٹھتے رہے۔تب بھی جب میرا حلقہ احباب بالکل بدل کر رہ گیا اور ہم خود ایک میز کی مستقل زینت بن گئے۔
حلقہ اربابِ ذوق اس وقت دو شاخوں میں بٹا ہوا تھا۔ادبی اور سیاسی۔سیاسی حلقے کا اجلاس وائی ایم سی اے کے بورڈ روم اور ادبی کا پاک ٹی ہاؤس کے بالا خانے پر ہوا کرتا۔میں دونوں حلقوں کے اجلاس میں بطور ناظر شرکت کرتا۔ایک حلقہ’ارباب ِقلم’بھی تھاجسے سیف زلفی چلا رہے تھے۔اس کی نشست جمعرات کو منعقد ہوتی۔ ‘پنجابی ادبی سنگت’کے اجلاس بھی وائی ایم سی اے ہی کے ایک کمرے میں ہوتے تھے۔ان سب کے پراگرام ٹی ہاؤس کی ونڈوز کے شیشوں پر چسپاں کر دیے جاتے تھے اور جس کا جدھر جانےکو جی چاہتا تھا چلا جاتا تھا۔اجلاس کا وقت ہونے پر پہلے شہرت صاحب اپنی نشست چھوڑ کر بالاخانے کی سیڑھیاں چڑھ جاتے۔پھر جس کا جی چاہتا ان کی پیروی کرتا۔تنقید کے لیے پیش کئے گئے ادب پارے پر مدلل بحث کی جاتی۔اختلاف کے پہلو بھی نکلتے۔میں نے کبھی کسی کے حق میں یا مخالفت میں ایک جملہ بھی نہیں کہا ہوگا مگر جب بحث کے نکات پر غور کرتا تو اسے اپنے ہی دل کی آواز جانتا۔ایک صاحب بات ختم کرتے تو احساس ہوتا اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں اور اسی میں سے دوسرے صاحب اختلاف کی صورت نکال لیتے تو میں اپنے آپ کو ان کا ہمنوا محسوس کرتا۔علی ظہیر منہاس اردو بازار چوک کی ایک عمارت کے ایک کمرے میں مقیم تھے۔اس لیے ان کے لیے ہر بار یہاں آنا ممکن نہیں تھا مگر اب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔اسرار زیدی صاحب سے تعارف کے بعد وہاں تنہا ہونے کا خوف جاتا رہا تھا۔ان کے ساتھ اور بھی کئی دوست اب میری آمد کے منتظر رہتے تھے اور میں نے اتوار کے علاوہ بھی وہاں جانا آغاز کر دیا تھا۔
علی ظہیر منہاس ہی کے کمرے میں اعزاز احمد آذر اور لطیف ساحل سے ملاقات ہوئی اور بہت جلد گہری دوستی میں بدل گئی۔وہ دونوں شاہدرہ میں مقیم تھے،جہاں مکان ایک دوسرے پر امڈے پڑتے تھے۔مجھے کبھی وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ شاہدرہ میں کہیں اندرون ِشہر کا منظر بھی دکھائی دے گا۔ظفر رباب کی رہائش بھی شاہدرے میں تھی۔ایک بار ظفر رباب کی طرف جانا ہوا تو اس کا ایک شعر شدّت سے یاد آیا اور اندازہ ہوا کہ ماحول شاعر کے اظہار پر کس طرح کے نقش مرتب کرتا ہے:
ہم وہاں رہتے ہیں جن گلیوں میں گھر
ایک دوجے کے سہارے ہیں کھڑے
یہی وہ فضا تھی جس میں بسر کر کے میں بی-اے کے دوسرے سال میں پہنچا۔اس سے پہلے اسلامک سمٹ کانفرنس ہو چکی تھی۔ہم نے فورٹریس اسٹیڈیم کے عوامی میلہ میں ٹیٹو شو کے ساتھ شہنشاہ ِایران کی جھلک بھی دیکھ لی تھی۔ایشیا کو سرخ اور سبز خانوں میں بٹتے دیکھا تھا۔ہاسٹل کے کامن روم کے ٹی وی پر ضیا محی الدین شو میں ایم اسلم کی درگت بنتے دیکھی تھی اور بہت کچھ جو اب تاریخ کا حصہ ہےمگر اب بنگلہ دیش نامنظور تحریک کا دور تھا۔لاہور کے طلبہ اس ضمن میں بہت فعال تھے۔کالج میں روز ہی ہنگامہ برپا ہوتا۔گیٹ کے سامنے کوتوالی ہونے کی وجہ سے جلوس کو روکنے کے لیے پولیس کو حرکت کرنے میں ذرا سی دیر لگتی۔آنسو گیس کے شیل پھینکے جاتے۔سب سے زیادہ مشکل میں ہم بورڈر ہوتے جو پولیس ریڈ کے ڈر سے اکثر بے گھر ہو جاتے۔یہی صورت طالب حسین کے کالج میں بھی چل رہی تھی۔بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کا غم مجھے بھی تھا مگر دو باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ایک یہ کہ اسے نامنظور کرنے سے کیا ہم تاریخ کے یک رخی اسراع کو موڑ سکتے ہیں؟اور دوسری یہ کہ احتجاج کرتے ہوئے قومی اثاثوں اور عمارتوں کی بربادی کیا ضروری ہے اور ان راہگیروں،مسافروں اور سفر پر نکلے لوگوں کا کیا قصور ہے،جن کی سواریاں نذرِ آتش کر دی جاتی ہیں۔ایک بار میں نے ایک عورت کو اپنے ہاتھوں سے جلا دی جانے والی ایک
موٹر بائیک کی آگ بجھانے کی کوشش کرتے دیکھا تو میرا جی ظلم اور بے دردی کے خلاف نفرت سے بھر گیا اور میرا دل سیاست دانوں اور ان کے گماشتوں سے ہمیشہ کے لیے کھٹّا ہو گیا۔
ایک دن جب پولیس ہاسٹل پر حملہ آور تھی اور ایک ایک کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ابّاجی کسی کام سے لاہور آئے اور ہم دونوں بھائیوں کو ملنے کی سبیل پیدا کی۔انہوں نے ہمیں سامان لپیٹنے کا کہا اور لے کر ڈپٹی صاحب کی طرف چلے آئے۔وہ رات ہم نے ان کے یہاں بسر کی۔یہی وہ رات تھی جب بشیر طارق(لبھّا) کو بے قصور گرفتار کیا گیا۔طالب علموں کو کوتوالی میں ننگا کر کے بٹھایا گیااور یہ خبر بی بی سی نے بریک کی۔بنگلہ دیش بن چکا تھا سو منظور ہو کر رہا اور دو قومی نظریہ منہ کے بل آ رہا مگر نہیں یہ تو اسی روز مرحوم ہو گیا تھا جب ہم نے مشرقی پاکستان میں غلامی کا بیج بویا تھا اور ایک عظیم فکری اور سیاسی روایت سے وابستہ قوم کو اس کی زبان سے محروم کر کے گونگا کرنے کی کوشش کی تھی۔
اس بار گاؤں آیا تو تلمبہ اور میاں چنوں کے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے سوا بڑی مصروفیت شاعری کا مطالعہ تھی۔کہیں اندر ایک طاؤس ِخود مست کی خود رفتگی کا غلبہ تھا اور وجہ بخوبی معلوم مگر اسے لکھنے میں جو مزہ تھا وہ کہنے میں تھا نہ بتانے میں۔میری سرمستی کا عالم یہ تھا کہ اپنے کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا،کبھی ڈم ڈم چلا آتا تو کچھ وقت اس کی معصومیت کی بھد اڑانے میں گزر جاتا۔بےچارہ کیسا سادہ اور صاف دل آدمی تھا اور مجھ پر ایسا اعتماد کہ میرے جھوٹ کو بھی سچ مان لیتا۔اُسے ہمارے وسیب کے لوگوں نے بہت لُوٹا مگر اس کے دل کی کشادگی میں کمی نہیں آئی۔
انہی دنوں ایک بار انیس انصاری اور علی ظہیر منہاس ملنے بستی آئے۔ان کی ملاقات حویلی کے دروازے پر پیپل کی چھاؤں میں میرے بڑے بھائی مہر نواب سے ہوئی۔میرے بارے میں استفسار پر بھائی نے میری موجودگی کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا حالانکہ میں مہینے بھر سے بستی میں تھا۔اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔وہ الگ مکان میں رہتے تھے اور میرے کمرہ بند ہونے کی وجہ سے انہیں گمان تھا کہ میں لاہور پلٹ چکا ہوں۔
یہی وہ دن تھے جب میری زبان کی مُہر ٹُوٹی اور میں نے اردو کے ساتھ پنجابی میں بھی لکھنا شروع کیا۔
درس گاہ – 45
اسلامیہ کالج لاہور میں میرے انگریزی کے استاد پروفیسر منہاج الدین،اکنامکس کے پروفیسر فیض الحسن گیلانی،پولیٹیکل سائنس کے سرور صاحب اور فارسی آپشنل کے ثنا اللہ صاحب تھے۔یہ چاروں اساتذہ مزاج کی چار اطراف کے نمائندہ تھے مگر ان کی کلاس میں جانا اور اپنی موجودگی کا احساس دلانا اچھا لگتا تھا۔
اب کی بار میں نے اپنی تعلیم کو سنجیدہ لینا شروع کیا اور اکنامکس کے پہلے ٹیسٹ میں اوّل آ کر خود پر اپنے اعتماد کو بحال کیا۔انگریزی اور دوسرے مضامین میں بھی میری کاکردگی بُری نہیں تھی پھر بھی ایک خاص طرح کا احساس ِزیاں تھا جو روح پر حاوی تھا اور اس کی وجہ اپنی زندگی کے دو قیمتی برسوں کا ضیاع تھا۔میرے ہم جماعتوں میں آصف،محمود اور نواز طاہر پنجاب یونیورسٹی پہنچ چکے تھے اور بالترتیب پبلک ایڈمسٹریشن،کیمسڑی اور اردو کے طالب علم تھے۔شکور اسی کالج میں بی ایس سی کے دوسرے سال میں تھے۔ہاں ایک جاوید منیر احمد تھے جو میری روایت نبھا رہے تھے اور اسی کالج میں میری طرح بی اے کر رہے تھے اور ہاسٹل میں چند کمرے دور رہتے تھے۔
پہلے ہی روز کلاس میں بشیر طارق( لبھّا)سے ملاقات ہوئی اور بہت جلد وہ میرے قریبی دوستوں میں شمار ہونے لگے۔یہ زمانہ میری تخلیقی شگفت کا تھا۔اسے میرے روم میٹ خان عبدالوحید رشی کی محبت اور سلیقے نے خوب پروان چڑھایا۔کمرے کی تزئین و آرائش میں انہیں یدِطولیٰ حاصل تھا۔وہی کمرہ جو شب کو خوابوں کی رہ گزر ٹھہرتا،صبح ہوتے ہی ڈرائنگ روم میں تبدیل ہو جاتا۔رشی صاحب کو بستر لپیٹنے اور اس کی آرائش سے چارپائی کو سوفہ میں بدلنے
میں ایسی مہارت تھی کہ کمرے کی فضا ہی بدل جاتی اور اس ہنر مندی کا اثر میری طبع پر بھی ہو رہا تھا۔وہ خوش لباس ہی نہیں خوش اطوار بھی تھے۔کالج یونیفارم کے علاوہ وہ ہم رنگ شلوار قمیص اور ویسٹ کوٹ میں ملبوس رہتے تھے اور میں نے کبھی انہیں ویسٹ کوٹ کے بغیر نہیں دیکھا۔
میں اور میرے دوستوں نے جلد ہی ہاسٹل میں عوامی مقبولیت حاصل کر لی اور میس مینیجر کے الیکشن میں پرانی انتظامیہ کو شکست دے کر جاوید منیر احمد کو یہ زمہ داری تفویض کی۔کالج کے معاملات میں بھی ہم کافی دخیل تھے اور میری ادبی زندگی بھی پہلے کے مقابلے میں کافی فعال تھی۔میں معقول ادبی پرچوں میں چھپ رہا تھا مگر ابھی کالج میگزین’فاران’میں شائع نہیں ہوا تھا۔نہ معلوم کیوں میں نے اس کے انچارج پروفیسر شہرت بخاری سے ملاقات کی نہ ہی مجلس ِادارت کے ارکان سے تعارف حاصل کیا تاہم فاران کے لیے طلبہ کو لکھنے کی دعوت کا نوٹس پڑھ کر میں نے دو غزلیں،دو نظمیں اور ایک افسانہ’زود پشیماں’جو ممو کے بارے میں لکھے میرے ہی افسانے کا تجدیدی اظہار تھا۔کالج میگزین کے لیے ڈراپ باکس کے حوالے ضرور کیے۔ان کے ساتھ ایک انشائیہ’دشمنی کا سلیقہ’بھی تھا اور مجھے دعویٰ ہے کہ وہ تحریر بُری نہیں تھی۔
تبھی میں نے کالج گزٹ کے انگریزی حصے کے مدیر کے لیے مقابلے میں حصہ لیا اور گزٹ کے انچارج میرے مضمون کی فوقیت کے قائل بھی تھے مگر کالج یونین نے پہلے ہی محمد جہانگیر (بعد میں لاہور کارپوریشن کے رکن اور ایم پی اے) کے حق میں فیصلہ کر رکھا تھا۔میری تالیف ِقلب کے لیے مجھے دوستی کا شرف بخشا گیا اور کامریڈ باقر اور دوسرے کار پردازان مجھے محبت سے ملنے لگے مگر میرے دل سے اپنی حق تلفی کا داغ اب تک نہیں گیا۔
کامریڈ باقر سے نسبت نے ایک بار عجب گل کھلایا۔کالج میں پروفیسر شہرت بخاری نے ایک عظیم مشاعرے کا اہتمام کیا تھا اور وہی اس کے منصرم تھے۔یہ مشاعرہ کالج ہال میں حفیظ جالندھری کی صدارت میں منعقد ہوا اور اس میں ظہیر کاشمیری،پروفیسر قیوم نظر اور انجم رومانی جیسے جید شعرا موجود تھے۔نوجوانوں میں مجھے سلیم شاہد کا نام یاد ہے۔میں اسے اگلی صف کے سامعین میں بیٹھ کر سُن رہا تھا اور شہرت صاحب نے کلام سنانے کے لیے ظہیر کاشمیری صاحب کے نام کا اعلان کیا تھا کہ کامریڈ باقر ہال میں وارد ہوئے اور مجھے سامعین میں دیکھ کر سٹیج پر شہرت صاحب کے پاس جا کر ان کے کان میں کچھ ایسا افسوں پھونکا کہ وہ کچھ پریشان بلکہ بوکھلائے ہوئے محسوس ہوئے۔پتا چلا کہ کامریڈ مشاعرے کے اس مرحلے پر مجھے پڑھوانے کے طلبگار ہیں اور ظاہر ہے شہرت صاحب اس کے لیے راضی نہیں تھے۔ظہیر صاحب نے بد مزگی سے بچنے کے لیے خود مجھے سٹیج پر آنے کی دعوت دی اور میں شرمندگی سے قعر ِمذلت میں دھنس کر رہ گیا مگر طلبہ کے اصرار پر مجھے ایک غزل سنانا ہی پڑی۔یہ الگ بات کہ میں نے کامریڈ باقر کو اور شہرت صاحب نے مجھے ایک مدت تک معاف نہیں کیا اور شاید اسی کا شاخسانہ تھا کہ فاران چھپ کر آیا تو اس میں میری کوئی تخلیق شامل نہیں تھی۔
مجھے فاران کے اگلے پرچے میں بھی شامل نہیں کیا گیا تو میں نے شہرت صاحب کے پاس جا کر اس بات کا شکوہ کیا۔اس پر انہوں نے فرمایا کہ کالج کے چھے ہزار طلبہ میں سے کم وبیش پانچ سو چھپنے کے لیے اپنی شاعری ہی دیتے ہیں اور فاران کے محدود صفحات پر سب کو جگہ دینا ممکن نہیں تو میں نے عرض کی کہ ان پانچ سو میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو خود شعر کہتے ہوں۔اب کے پروفیسر صاحب کا جواب تھا’شاید پانچ یا چھ’تو میں نے گزارش کی کہ ان پانچ میں سے ایک میں ہوں اور اسی پر بس نہیں میں اپنی تعلیم مکمل کرنے اور عملی زندگی کا آغاز کرنے کے بعد بھی شعر کہتا رہوں گا اور شاید میں اُن دو لوگوں میں سے ایک ہوں گا جو ہمیشہ اس تخلیقی عمل کو جاری رکھیں گے تو پروفیسر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی۔شاید وہ اس دعوے کو مجذوب کی بڑ سمجھے تھے مگر حیرت اس بات پر ہے کہ وہ میرے اس دعوے کو کبھی بھولے نہیں۔کوئی بیس برس بعد جب وہ لندن جلا وطنی کے بعد لاہور پلٹے اور محترمہ کشور ناہید نے میری ملتان سے لاہور آمد پر میرے اعزاز میں اپنے گھر پر عشائیہ دیا تو اس میں انتظار حسین،زاہد ڈار،ذوالفقار احمد تابش،جاوید شاہین،اصغر ندیم سیّد اور دوسرے دوستوں کے علاوہ شہرت صاحب بھی موجود تھے۔کشور آپا نے مجھے کلام سنانے کو کہا تو میرے شعر پڑھنے سے پہلے شہرت صاحب نے اپنی گفتگو میں اقرار کیا کہ میں نے برسوں پہلے اپنے کہے کو سچ کر دکھایا ہے اور وہ میری اس مستقل مزاجی پر بہت شادماں ہیں۔
شہرت صاحب سے اس مکالمے کا فائدہ یہ ہوا کہ فاران کے اگلے شمارے میں میری دو نظمیں،دو غزلیں اور انشائیہ موجود تھے۔اسی زمانے میں علی ظہیر منہاس،ظفر رباب،علی نوید بخاری اور انیس انصاری سے بھی تعلق بنا اور ہم سب جلد ہی گہرے دوست بن گئے۔یہ چاروں احباب فاران کی مجلس ِادارت کے رکن تھے اور بلاشبہ ان کے زمانے میں فاران کے شائع ہونے والے شمارے بہت معیاری تھے۔سبطِ حسن کے معروف جریدے’پاکستانی ادب’میں شائع ہونے والی غزل جو میرے کسی مجموعہ کلام میں شامل نہیں کا یہ مقطع اسی نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔
خاموش سّنو ساجد و منہاس،ظفر کو
ہم اور ابھی اور ابھی اور کہیں گے
تب دن کالج کے ہنگاموں میں گزر جاتا تھا اور شام کو میں بشیر طارق کو ساتھ لے کر اپنے میاں چنوں اور ساہیوال کالج کے دوستوں کے ساتھ نششت جماتا تھا۔یہ وہ دور تھا جب میں نے پروفیسر علی عباس جلالپوری کی’روح ِعصر’اور ڈاکٹر وزیر آغا کی’تخلیقی عمل’سے آغاز کیا اور پھر خرد افروزی سے متعلق جو دستیاب ہوا،پڑھتا چلا گیا۔کالج ہاسٹل کے سامنے لوئر مال پار کرتے ہی گول باغ اور دائیں گھوم کر میونسپل کارپوریشن کے فوّارے کا اندرونی احاطہ ہماری نشست کا محل ہوا کرتا تھا اور ہم دنیا جہان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ایک دن فوارے کے دائرے میں ہمارے مابین روح کی ماہیت پر بحث چل رہی تھی کہ میں نے سیاہ چھڑی تھامے ایک وجیہہ بزرگ کو ہمارے گرد دائرے میں گھومتے دیکھا۔کچھ دیر بعد وہ اجازت لے کر ہمارے درمیان آ بیٹھے اور موضوع سے متعلق بات کر کے ہمارے فکری مغالطوں کو رفع کیا۔ہم نے تعارف چاہا تو انہوں نے’آپ سب کا ایک نوجوان دوست’کہہ کر ٹال دیا۔یہ نوجوان کبھی مجھے پرانی کتابوں کی دکانوں پر گھومتے مل جاتے کبھی مال پر ٹہلتے ہوئے۔دو ایک بار انہیں میں نے کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے بھی دیکھا مگر میرے قریب کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو مجھے ان کے بارے میں کچھ بتا سکتا۔دو یا تین برس کے بعد ایک دن میں نے فٹ پاتھ سے’نقش ِچغتائی’خریدی اور اس کی ورق گردانی کرتے ہوئے مجھ پر یہ بھید کُھلا کہ میرے نوجوان دوست کوئی اور نہیں بذات خود مصور ِمشرق ہیں مگر اس کے بعد وہ مجھے مدتوں دکھائی نہیں دیے اور جب میں ان کے گھر کا کھوج لگا کر ایک مہربان پبلشر اور ادیب دوست کے ساتھ ان کی طرف جانے کا وقت طے کر رہا تھا،پتا چلا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔باری تعالیٰ کی طرف سے ایسی عنایت اور ایسی محرومی کسی اور کی قسمت میں شاید ہی لکھی گئی ہو۔
درس گاہ – 44
میں1971ء کے وسط میں میاں چنوں پلٹ آیا تھا۔اس بار زیادہ تر نشست اپنے محلّےدار سرور اور جاوید(ڈم ڈم)سے رہی۔اتوار کو اگر میں شہر میں ہوتا تھا تو آصف،جمیل،ضیا،اعجاز،لیاقت،بِلّو اور محمود سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی مگر میرے علاوہ سب اپنی تعلیم میں مگن تھے۔ممتاز کے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ تعلیم جاری رکھ سکتا سو اس نے فوج میں کمیشن حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد ریلوے میں کوئی معمولی ملازمت کر لی تھی۔
اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے دو برس کس بےدردی سے برباد کیے۔سب دوست آگے بڑھ چکے تھے اور میں تھا کہ ابھی اپنی سمتِ سفر کا تعین ہی نہیں کر پایا تھا مگر اب انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔اس انتظار میں مَیں کبھی گاؤں جا بستا کبھی شہر۔شاعری پڑھ ہی نہیں کر بھی رہا تھا اور رسائل کے مطالعے کا سلسلہ جاری تھا۔مہر فلک شیر سنپال سے ملاقات نسبتاً بڑھ گئی تھی اور انہوں نے’مشاعرہ’کے نام کا ایک کتابچہ مجھے تحفے میں دیا تھا جو تلمبہ میں ہونے والے ایک مشاعرہ کی روداد تھی اور اس کا دیباچہ،جو تلمبہ کی تاریخ اور فکری روایت کا عمدہ محاکمہ کرتا تھا،خادم رزمی کا لکھا ہوا تھا جن کی ایک غزل میں نے تازہ اوراق میں پڑھی تھی اور اس کے دو شعر مجھے ازبر ہو گئے تھے:
میں اکیلے پن کا مارا گھر سے نکلا تھا مگر
رونق ِ بازار تُو نے اور تنہا کر دیا
کس نے لہرائی دریچے سے بدن کی چاندنی
کون تھا میلی گلی کو جس نے اُجلا کر دیا
اتفاق سے اگلے ہی دن سجّاد پاندھا ملنے چلے آئے تو میں نے ان سے رزمی صاحب کے بارے میں بات کی کہ اُن کا تلمبے تواتر سے آنا جانا رہتا تھا۔حُسن ِاتفاق سے وہ رزمی صاحب کو جانتے تھے اور مجھے لےجا کر ملانے پر تیّار ہو گئے۔ان کے پاس موٹرسائیکل تھا۔ہم نے ایک ٹیپ ریکارڈر پکڑا اور رزمی صاحب کے سکول جا پہنچے۔وہ پرائمری کی دو کلاسز کو یک جان کیے کچھ رٹوا رہے تھے اور فارغ ہونے ہی والے تھے۔ابھی تعارف کی رسم ادا ہو رہی تھی کہ چھٹی کی گھنٹی بج گئی اور وہ ہمیں سکول کے دروازے کے سامنے اپنی بیٹھک میں لے آئے۔میں نے محسوس کیا کہ ایک پرستار کی آمد پر وہ مضطربانہ مسرور ہیں اور اس مسرت میں اس وقت دونا اضافہ ہو گیا جب میں نے’اوراق’کا ذکر کر کے وہی غزل سنانے کی فرمائش کی۔پھر ان کی بہت سی غزلیں سُنی اور ریکارڈ کیں۔ان کے اصرار پر ایک اپنی غزل بھی سنائی جو یقیناً اصلاح طلب تھی مگر انہوں نے کُھل کر داد دی اور کسی روز میرے گھر پر آنے کی نوید دے کر ہمیں رخصت کیا۔
رزمی صاحب سے اگلی ملاقات کی نوبت بھی جلد ہی آ گئی۔انہوں نے مجھے خان غضنفر روہتکی سے ملوایا جو بازار میں کریانے کی دکان کرتے تھے اور فی البدیہ شعر کہنے میں یدِطولیٰ رکھتے تھے۔اُسی ہفتے تلمبہ میونسپل کمیٹی کا کوئی مشاعرہ برپا ہونے والا تھا اور خان صاحب ہی اس کی صدارت کر رہے تھے۔انہوں نے مجھے مشاعرہ پڑھنے کی دعوت دی اور میں نے اپنی زندگی کا وہ پہلا مشاعرہ چند مقامی شاعروں پر تفوق پا کر پڑھا۔سب نے میری خوب خوب حوصلہ افزائی کی اور مجھے مبتدی یا اس کُوچے میں نووارد ہونے کا احساس نہیں دلایا۔اسی مشاعرے میں کئی اور شاعروں سے تعارف ہوا جن کا کلام میں نے کتابچے میں پڑھا تھا۔ان میں صادق سرحدی،یعقوب مومن اور ساغر مشہدی خصوصیت سے ذکر کرنے کے قابل ہیں۔خصوصاً ساغر مشہدی صاحب سے طویل رفاقت رہی اور یہ نسبت اب تک برقرار ہے۔
اگلے چند دنوں میں رزمی صاحب اور ساغر مجھے گاؤں ملنے آئے تو رزمی صاحب کے اصرار پر میں نے اپنی بیاض انہیں ملاحظے کے لیے پیش کی۔انہوں نے بہت رغبت سے اسے دیکھا اور چند مقامات کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہاں فلاں لفظ کے درست تلفظ کا استعمال نہ ہونے کے باعث مصرع محل ِنظر ہے مگر انہوں نے قلم لگانے کی بجائے مجھے اساتذہ کے کلام سے سند لانے کی صلاح دی اور میں نے اُن کے مشورے پر صاد کیا۔پھر ان ملاقاتوں میں تسلسل آنے لگا اور ایک دوسرے کا کلام سُنا جانا معمول بن گیا۔میں تسلیم کرتا ہوں کہ کہیں اندر ہی اندر میری تربیت ہو رہی تھی اور مجھے اپنی ذات اور شاعری پر اعتماد ہونے لگا تھا۔اب میں شاعری پڑھتے ہوئے اس کے آہنگ اور الفاظ کے معیاری تلفّظ پر دھیان دینے لگا تھا اور اسی دوران میں میں نے اپنی کچھ غزلیں’نئی قدریں،اوراق،نیا دور اور’افکار’ کو بھجوائیں۔
ادبی پرچوں کے وقت پر شائع ہونے کی روایت تب تھی نہ اب مستحکم ہوئی ہے۔پھر ملکی حالات دگرگوں ہونا بھی ایک وجہ رہی ہو گی یا ممکن ہے بنیادی مسئلہ ایک نئے شاعر کے ظہور کو قدرے مؤخر کرنا ہو۔یہ غزلیں چھپ تو گئیں مگر سقوطِ مشرقی پاکستان کا سانحہ برپا ہونے کے بعد۔تب تک میں دوبارہ لاہور پہنچ چکا تھا اور ڈھاکہ فال کے سانحے سے بہت دل برداشتہ تھا۔19 برس کی عمر تھی مگر لگتا تھا سب کچھ مٹ گیا ہے اور ہمارے قدموں تلے زمین نام کی کسی شے کا وجود نہیں۔ہم کسی نظریے اور سمت کے تعین سے معذور ہیں اور نہیں جانتے کہ اپنی شناخت کے لیے کس تہذیب اور معاشرت کی طرف دیکھیں۔
سب سے پہلے مجھے’نئی قدریں’نے چھاپا،پھر’نیا دور’اور بعد میں ‘اوراق’ نے.بہت دیر بعد اندازہ ہوا کہ’نئی قدریں’،کے ایڈیٹر ہر غزل’جیسا ہے جہاں ہے’کی بنیاد پر شائع کرتے ہیں اور اکثر سالانہ خریدار بنانے کے تنطیمی دورے پر رہتے ہیں۔اس سلسلے میں انہوں نے یہ کمال دکھایا کہ ایک بار میرے گاؤں بھی چلے آئے تھے اور میں نے اپنے متعدد دوست ان کے پرچے کے خریدار بنوا دیے،جنہیں ایک ہی شمارہ خریداری کی مد میں عنایت کیا گیا۔خیر انہیں اس سے زیادہ کی طلب ہی نہیں تھی البتہ ہر شمارے میں میری کوئی تخلیق شامل ہونے کی وجہ سے وہ ایک شمارہ مجھے ضرور بھجوا دیتے تھے اور بعض اوقات میں ‘گوشہء ادب’ سے خرید لیتا تھا۔
افکار کے صہبا لکھنوی صاحب نے کہیں میرا کوئی مزاحیہ مضمون پڑھا تھا اور مصر رہے کہ میں شاعری ترک کر کے مزاح میں نام پیدا کروں۔ان کا ادعا تھا کہ مزاح میں نام پیدا کرنا بہت آسان ہے اور شاعری میں اب کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔انہوں نے اس قدر اصرار کیا اور اپنی تجویز کے حق میں اتنے پوسٹ کارڈ بھجوائے کہ مجھے چڑ سی ہو گئی اور میں نے’افکار’میں لکھنے کا ارادہ ہی ترک
کر دیا۔’افکار’میں چھپنے والی میری اکلوتی تحریر ایک افسانہ’آنے والے کل کی بات’تھا۔یہ ایک علامتی افسانہ تھا اور اس کا پس منظر سقوطِ ڈھاکہ ہی تھا۔بعد میں میں نے اسے پنجابی میں ترجمہ کر لیا اور یہ میری پنجابی کہانیوں کی کتاب’نیندر بِھنّی رات’میں ‘کل تے بھلکے’ کے عنوان سے شامل ہوا۔
تھرڈ ائیر کے داخلے شروع ہوئے تو میں آئی کام میں بھی کامیاب ہو گیا تھا مگر اس سلسلے کو حاکم کے اصرار کے باوجود میں نے وہیں بند کر دیا اور بی۔اے میں داخلے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں درخواست جمع کرائی۔اس بار میں لا کالج ہاسٹل میں ٹھہرا جہاں نواز طاہر اب ایم۔اے اردو کا طالب علم تھا۔میرٹ لسٹ دو روز بعد لگی تو اس میں میرا نام موجود نہیں تھا۔دوسری میرٹ لسٹ دوسرے روز آویزاں کی جانا تھی۔میں نے اس کا انتظار ہی نہیں کیا اور اسلامیہ کالج سول لائنز آ کر داخلہ فارم بھر کر جمع کرا دیا۔کلرک نے انتظار کرنے کو کہا اور کوئی پندرہ منٹ کے بعد مجھے پرنسپل خواجہ محمد اسلم کے کمرے میں انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا۔کمیٹی نے ایک ہی سوال پوچھا کہ میٹرک اور انٹر میں چار سال کا تفاوت کیوں ہے تو میں نے عرض کیا کہ میری حماقت کی وجہ سے۔داخلہ فارم پر دستخط کر کے مجھے فیس جمع کرانے کو کہا گیا جو میں نے فوراً کالج میں موجود بنک برانچ میں جمع کرا دی۔پھر ہاسٹل داخلے کی کارروائی مکمل کی اور دوپہر تک میں ایک کمرے کا مالک بن چکا تھا،جو مجھے ایک اور طالب علم کے ساتھ شئیر کرنا تھا۔
اگلے روز میں یونہی گورنمنٹ کالج گیا تو وہاں دوسری لسٹ آویزاں کی جا چکی تھی اور میرا نام سب سے اوپر موجود تھا۔راز یہ کُھلا کہ کل کی لسٹ اولڈ سٹوڈنٹس کی تھی اور آج کی باہر سے داخلہ لینے والے طلبہ کی۔کل میں نے اس نکتے پر غور ہی نہیں کیا تھا۔اب معاملہ کُھلا تو قدرے افسوس تو ہوا مگر اس قدر نہیں کہ میں اسلامیہ کالج میں ادا کی گئی رقم سے درگزر کرتا ۔میں نے اسے اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا اور اسلامیہ کالج ہی کو اپنی اگلی درس گاہ ٹھہرایا۔اس بار میرے مضمون اکنامکس اور پولٹیکل سائنس تھے اور فارسی بطور اختیاری مضمون کے۔نہ معلوم کیوں میں نے اس بار بھی اردو کا انتخاب نہیں کیا۔
کلاسز شروع ہونے تک کا وقت میں نے گاؤں میں گزارا۔اس دوران میں میرا چھوٹا بھائی طالب حسین بھی میڑک کر کے لاہور آ گیا تھا اور اب ایم اے او کالج کا طالب علم تھا اور دلاور ہاسٹل میں قیام پذیر۔زندگی اپنی درست نہج پر چل پڑی تھی۔کریسنٹ ہاسٹل میں مجھے کمرہ نمبر 184 الاٹ کیا گیا اور کوئٹہ کے ایک نوجوان عبدالوحید رشی میرے روم میٹ بنے۔وہ تواضع اور سلیقے کا مرقع تھے۔وہی کمرہ جو رات کو خواب گاہ ہوا کرتا تھا،ان کی سلیقہ مندی سے دن کو ڈرائنگ روم میں بدل جاتا تھا۔دن میں وہ رضائیوں کو اس طرح لپیٹ کر چارپائی پر سجاتے تھے کہ وہ بیٹھنے والوں کا تکیہ بن جاتی تھیں۔سجاوٹ،صفائی ستھرائی اور کمرے سے متعلق ہر کام انہوں نے اپنے ذمے لے کر مجھے آزاد چھوڑ دیا تھا مگر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ وہی سلیقہ مجھ میں بھی پروان چڑھ رہا ہے۔میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری ذات کے اثبات میں ان کا حصّہ مجھ سے بڑھ کر ہے۔
کالج پہنچا تو پتا چلا کہ میرے ساہیوال کے دوستوں میں سے شکور اور جاوید منیر احمد اسی ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں۔شکور بی۔ایس۔سی کر رہا تھا اور جاوید بی۔اے،اس لیے اجنبیت کا احساس پہلے ہفتے ہی جاتا رہا اور سب کچھ اپنا اپنا سا لگنے لگا تاہم ملکی حالات دگرگوں ہی تھے۔ایک روز لاہور کی فضاؤں میں توپوں کی دنادن اور طیاروں کی گھن گرج سُنائی دی تو پتا چلا کہ جنگ چھڑ گئی ہے۔لاہوری اس بار بھی یہ مناظر چھتوں پر چڑھ کر دیکھتے تھے کہ کالجز بند کر دیے گئے اور تمام طالب علموں کو گھر جانے کو کہہ دیا گیا۔ہم دونوں بھائی اپنا سامان لیے بادامی باغ بسں اسٹینڈ کو جاتے تھے کہ مینار ِپاکستان کے قریب ہوائی حملے کا سائرن بجا اور سواریاں تانگے سے اتر کر پودوں کی اوٹ میں ادھر ادھر لیٹ گئیں۔تب کسی طیارے سے ایک برسٹ ہماری طرف آیا اور زمین پر جیسے پھول کھلنے لگے۔پل بھر دو طیارے ان کے تعاقب میں آئے اور سب ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔اللہ کا کرم ہوا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ہم اسی شام خیریت سے اپنے گاؤں پہنچ گئے کہ ہمارے لاہور شفٹ ہونے کے بعد ابّا جی نے میاں چنوں کی رہائش ترک کر دی تھی۔
سقوط ِمشرقی پاکستان کی خبر میں نے اپنی بستی میں سُنی۔